#کلاسیکی ادب
Explore tagged Tumblr posts
Text
صفر کی توہین سلسلہ کلامیہ اور الحاد پرستی کے تناظر میں – ا شترا ک
صفر کی توہین سلسلہ کلامیہ اور الحاد پرستی کے تناظر میں – ا شترا ک
صفر کی توہین سلسلہ کلامیہ اور الحاد پرستی کے تناظر میں – ا شترا ک — Read on ishtiraak.com/index.php/2022/09/22/sifar-ki-tauheen/
View On WordPress
#feministwriter womanday nadiaumberlodhi#Khabrain Manchester newspaper#Nadia umber Lodhi editor#Parveen Shakir poetess by Nadia Umber Lodhi poetess#مضامین#نادیہ عنبر لودھی کی شاعری اور نثر#کلاسیکی ادب#اردو شاعرات#اسلام آباد کی کالم نگار#طنز ومزاح
0 notes
Text

میں تم سے ہٹ کر
تیرے دھیان میں چلا جاتا ہوں
اور میرا دھیان تمہارے دلائل کی بجائے
تمہارے دلائل کی خوبصورتی میں ہی الجھ جاتا ہے
جیسے کلاسیکی ادب پڑھتے ہوئے
ہم لکھاری کے خلاف دلائل نہیں دیتے
چپ چاپ مان لیتے ہیں
نئے خیال کا انداز
کس قدر خوبصورت ہے
اور میں بحث ہارنے لگتا ہوں
سو میں بحث کل پر رکھتا ہوں
کہ آج کی رات
میں تمہارے دلکش روئیے کے ساتھ
ادھر ہی رکتا ہوں
امید ہے کل صبح
تم اسے ایک خواب سمجھو گی
اور ہم پھر کسی
کورٹ رووم میں
ایک دوسرے کے خلاف
دلائل دے رہے ہوں گے
وقار کنول
2 notes
·
View notes
Text
ناصر زیدی : حق گوئی ہی ہے جرم اگر، تو یہ بھی بھاری مجرم ہیں
یُوں تو ہم عصری کا اطلاق ہمارے اردگرد کے بے شمار لوگوں پر ہوتا ہے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کا لڑکپن اور فنی کیرئیر کم و بیش ساتھ ساتھ گزرتا ہے اور یوں آپ انھیں اپنی آنکھوں کے سامنے اور اپنے ساتھ ساتھ بڑھتا اور سنورتا دیکھتے ہیں۔ ناصر زیدی کا شمار بھی ایسے ہی دوستوں اور ہم عصروں میں ہوتا تھا۔ اسکول کے زمانے میں وہ عطاء ا لحق قاسمی کا ہم جماعت تھا اور دونوں کے دوستانہ تعلقات میں اس زمانہ کا لڑکپن بڑھاپے تک قائم رہا، عطا اُسے پُھسپھسا اور وہ ا ُسے مولوی زادہ کہہ کر بلاتا تھا ۔ دونوں ہی بندہ ضایع ہو جائے پر جملہ ضایع نہ ہو کے قائل تھے سو اُن کی موجودگی میں کسی محفل کا سنجیدہ یا بے رنگ رہنا ممکن ہی نہیں تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اسّی کی دہائی میں ایم اے او کالج کے شعبہ اُردو میں ناصر اپنے مخصوص بیگ اور دراز زلفوں کے ساتھ مسکراتا ہوا میرے اور عطا کے مشترکہ کمرے میں داخل ہوا اور ایک کتاب میز پر رکھتے ہوئے بولا، ’’اوئے مولوی زادے دیکھ میری کتاب کا دوسرا ایڈیشن آگیا ہے ‘‘
عطا نے پلکیں جھپکائے بغیر کہا۔’’پہلا کدھر گیا ہے؟‘‘ اور لطف کی بات یہ ہے کہ اس جملے کا سب سے زیادہ مزا خود ناصر زیدی نے لیا اور اسی حوالے سے بھارتی مزاح نگار مجتبیٰ حسین کا وہ مشہور جملہ بھی دہرایا کہ ’’جو صاحب اس کتاب کے دوسرے ایڈیشن کی ایک کاپی خریدیں گے انھیں پہلے ایڈیشن کی دو کاپیاں مفت پیش کی جائیں گی‘‘۔ اندرون ملک مشاعروں اور ادبی تقریبات کے حوالے سے ہم نے بے شمار سفر ایک ساتھ کیے ہیں ۔ اس کی نہ صرف آواز اچھی تھی بلکہ ریڈیو کی ٹریننگ نے اُسے اور نکھار دیا تھا اس پر اُس کی یادداشت اور ذوقِ مطالعہ نے مل کر اُسے ریڈیو، ٹی وی اور دیگر مشاعروں کا مستقل میزبان بنا دیا تھا ۔ جزوی نوعیت کی ملازمتوں سے قطع نظر وہ سار ی عمر تقریباً ف��ی لانسر رہا اور غالباً سب سے زیادہ عرصہ اُس نے ماہنامہ ’’ادبِ لطیف‘‘ کی ادارت میں گزارا ۔ اتفاق سے وفات کے وقت بھی ایک بار پھر وہ اُسی رسالے سے منسلک تھا۔
صدیقہ جاوید کی وفات کے باعث رسالے کے مالی معاملات اُس کی ذاتی صحت اور گھریلو مسائل کی دیرینہ پیچیدگیوں نے اُس کی صحت پر بہت بُرا اثر ڈالا تھا جس کا اثر اس کی نقل و حرکت اور طبیعت کی شگفتگی پر بھی پڑا تھا کہ گزشتہ چند ملاقاتوں میں وہ پہلے جیسا ناصر زیدی نہیں رہا تھا ۔ جہاں تک کلاسیکی شاعری اور اشعار کی اصل شکل اور صحت کا تعلق ہے اُس کا مطالعہ بہت اچھا تھا اور اس سلسلے میں وہ اکثر اپنے ’’مستند‘‘ ہونے کا اظہار بھی کرتا تھا اور یہ اُسے سجتا بھی تھا کہ فی زمانہ ’’تحقیق‘‘ کی طرف لوگوں کا رجحان کم سے کم ہوتا جا رہا ہے ۔ ضیاء الحق کے زمانے میں وہ کچھ عرصہ سرکاری تقریریں لکھنے کے شعبے سے بھی منسلک رہا جس پر بعد میں اُسے تنقید کا بھی سامنا رہا خصوصاً اسلام آباد ہوٹل میں روزانہ شام کو احمد فراز کی محفل میں اس حوالے سے ایسی جملہ بازی ہوتی تھی کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ جہاں تک اُس کا شاعری کا تعلق ہے وہ اپنی اٹھان کے زمانے کے ہم عصروں سرمد سہبائی ، عدیم ہاشمی، اقبال ساجد، ثروت حسین، جمال احسانی ، غلام محمد ناصر، خالد احمد، نجیب احمد، عبید اللہ علیم، نصیر ترابی اور دیگر کئی نئی غزل کے علمبرداروں کے مقابلے میں اُسی روائت سے جڑا رہا جو کلاسیکی اساتذہ اور اُن کے رنگ میں رنگی ہوئی نسل کے شعرا میں زیادہ مقبول تھی اس کی ایک غزل اور ایک سلام کے چند اشعار دیکھئے۔
جذبات سرد ہو گئے طوفان تھم گئے اے دورِ ہجر اب کے ترے ساتھ ہم گئے
کچھ اس ادا سے اُس نے بُلایا تھا بزم میں جانا نہ چاہتے تھے مگر پھر بھی ہم گئے
مہلت نہ دی اجل نے فراعینِ دِقت کو قسطوں میں جی رہے تھے مگر ایک دم گئے
وہ ساتھ تھا تو سارا زمانہ تھا زیرِ پا وہ کیا گیا کہ اپنے بھی جاہ و حشم گئے
ہر چند ایک ہُو کا سمندر تھا درمیاں مقتل میں پھر بھی جانِ جہاں صرف ہم گئے
ناصرؔ نہیں ہے مجھ کو شکستِ انا کا غم خوش ہُوں کسی کی آنکھ کے آنسو تو تھم گئے
مرثیے اور سلام پر اُس نے کام بھی بہت کیا ہے اور لکھا بھی بہت ہے ایک سلام کے چند شعر دیکھئے
ذکر جو روز و شب حسینؔ کا ہے معجزہ یہ عجب حسینؔؓ کا ہے
دل میں جو بُغض پنج تن رکھّے وہ کہے بھی تو کب حسینؓ کا ہے
سرِ نیزہ بلند ہے جو سر با ادب ، باادب حسینؓ کا ہے
قلب و جاں پر فقط نہیں موقوف میرا جو کچھ ہے سب حسینؓ کا ہے
اسی دوران میں نقاد اور افسانہ نگار رشید مصباح اور شاعر افراسیاب کامل بھی اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گئے ہیں، رب کریم ان سب کی روحوں پر اپنا کرم فرمائے۔
امجد اسلام امجد
بشکریہ ایسکپریس نیوز
4 notes
·
View notes
Photo

قراۃ العین حیدر
آج اردو ادب کی مشہور ناول نگار اور افسانہ نگار قراۃ العین حیدر کی برسی ہے ۔ August 21, 2007 اردو ادب کی تاریخ میں قرۃ العین حیدر جیسے خوش نصیب لوگ کم ہی ہوں گے۔ جنھوں نے لازوال شہرت حاصل ہونے کے ساتھ ساتھ بھرپور زندگی نہایت فراغت سے گزاری۔ ان کے لیے اگر یہ کہا جائے کہ وہ چاندی کا چمچہ منہ میں لے کر پیدا ہوئی تھیں۔ تو بالکل بھی غلط نہ ہو گا۔ بات صرف دولت و شہرت تک محدود نہیں۔ بلکہ ننھیال، ددھیال دونوں علمی و ادبی، خانوادے ۔۔۔۔ جس پر انھیں بجا طور پر فخر بھی تھا اور جس کا اظہار انھوں نے اپنے سوانحی ناول ’’کار جہاں دراز ہے‘‘ میں جگہ جگہ کیا ہے۔ بعض ناقدین ادب نے اسے ’’فیملی ساگا‘‘ کا نام دیا ہے۔ لیکن اس سے اس کی اہمیت کم نہیں ہوتی ’’کار جہاں درا ز ہے‘‘ کے تین حصے ہیں۔ قرۃ العین حیدر 20جنوری 1926ء کو علی گڑھ میں پیدا ہوئیں اور 21 اگست 2007 کو دلی میں وفات پائی۔ بے شمار انعامات حاصل کیے۔ چار افسانوی مجموعے، پانچ ناولٹ، آٹھ ناول، گیارہ رپورتاژ کے علاوہ بے شمار کتابیں مرتب کیں۔ تقریباً گیارہ مختلف زبانوں کی کتابوں کا اردو میں ترجمہ کیا۔ چار کتابوں کا اردو سے انگریزی میں ترجمہ کیا۔ ساتھ ہی بچوں کے لیے بھی کئی کہانیوں کی کتابیں لکھیں ۔۔۔۔ ان کی زندگی دیکھئے تو صرف اور صرف ’’کام‘‘ ہی نظر آتا ہے۔۔۔۔ پتہ نہیں اتنی خوبصورت نثر لکھنے والی کا مزاج کیوں برہم رہتا ہے۔۔۔۔۔ اس حد تک کہ لوگ ملنے سے کتراتے تھے، بات کرتے ہوئے ڈرتے تھے۔۔۔۔۔ اس کی وجہ میری جو سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ ایک تو انھیں منافقت نہیں آتی تھی دوسرے انھوں نے ایک بھرپور اور توانا تہذیب کو دم توڑتے، بکھرتے دیکھا، صدیوں کے رشتوں کو پامال ہوتے دیکھا۔ ان ہمسایوں کو چھریوں سے ایک دوسرے کو گھائل کرتے دیکھا، جنھوں نے دیوالی پہ چراغ ساتھ جلائے تھے۔ جنھوں نے عید پہ سویاں ایک ہی پلیٹ میں کھائی تھیں، جن کے بچوں نے پتنگیں ساتھ اڑائی تھیں۔ جن کی عورتوں نے سہاگ کی مہندیاں ساتھ ساتھ لگائی تھیں اور دوپٹہ بدل بہنیں بنی تھیں۔ جن کی کنواری لڑکیوں بالیوں نے ساون میں جھولے ساتھ جھولے تھے۔۔۔۔ پھر جب وہ اپنی والدہ کے ساتھ پاکستان آئیں۔ تو یہاں ’’اسلام پسندوں‘‘ کا حقیقی چہرہ دیکھ کر حیران رہ گئیں، جو ایک آزاد ملک میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ اپنے ان ہم مذہبوں کو دیکھ کر رنجیدہ ہو رہی تھیں۔ جنھوں نے بڑی قربانیوں سے دو قومی نظریے کی بنا پر یہ ملک حاصل کیا تھا لیکن اب آپس ہی میں زبانوں، مسلکوں اور علاقائی بنیاد پر لڑ رہے تھے۔ تب انھوں نے سوچا کہ آخر جب آپس ہی میں لڑنا مرنا تھا تو اس کے لیے ملک تقسیم کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ یہ کام تو وہاں بھی ہو سکتا تھا ۔۔۔۔۔ لیکن وہاں لڑائی ہندوؤں اور سکھوں سے تھی، مسلمان آپس میں متحد تھے۔۔۔۔ شاید مسلمانوں کو آپس ہی میں لڑنے مرنے کے لیے ایک علیحدہ ملک کی زیادہ ضرورت تھی۔ جہاں وہ آرام سے ایک دوسرے کی بوٹیاں نوچ سکیں، ایک دوسرے کو اپاہج کر سکیں، اور اپنی عبادت گاہوں اور مزارات کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر سکیں۔ تیسرے یہ کہ ’’آگ کا دریا‘‘ جیسا معرکتہ الآرا ناول لکھنے کے بعد بیوروکریسی کا منفی رویہ اور کچھ اپنے ہی نام نہاد دوستوں کی منافقت نے ان کا دل توڑ دیا۔ چونکہ وہ بہت حساس تھیں، ہر فنکار کی طرح۔ اس لیے یہ سب سہہ نہ سکیں اور مولانا ابوالکلام آزاد کے تاریخی خطبے کو یاد کرتی ہوئی، آنسوؤں سے جھلملاتی آنکھوں کے ساتھ یہاں سے چلی گئیں۔ اور شہرت کی بلندیوں پہ پہنچ کے امر ہو گئیں۔ شاید پاکستان میں انھیں وہ مقام نہ ملتا جو بھارت میں ملا۔ دراصل وہ ایک ایسا سورج تھیں جس کی آب و تاب کے سامنے تمام ستارے ماند پڑ جاتے ہیں۔ ستارے بھلا سورج کی تابناکی کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ قرۃ العین حیدر پاکستان میں پی آئی اے سے بھی وابستہ رہیں بلکہ خواتین فضائی میزبانوں کی روایت انھوں ہی نے ڈالی۔ اس وقت ایئرہوسٹس کے طور پر لڑکیوں کو ملازمت کے لیے آمادہ کرنا بہت مشکل تھا۔ لیکن انھوں نے یہ بیڑہ اٹھایا اور ذاتی تعلقات اور اثر و رسوخ استعمال کر کے لڑکیوں کو اس طرف لے آئیں۔ ��س دن فلائٹ جانی تھی اس سے ایک دن پہلے بڑے جوش و خروش سے ریہرسل کروائی۔ اس حوالے سے وہ بہت پر جوش اور خوش تھیں۔ لیکن صرف ایک دن پہلے بڑے صوبے کے ایک بیوروکریٹ کی سفارش علاقائی بنیادوں اور تعلقات کی بنا پر ایک ایسے صاحب کے لیے آ گئی، جن کا اس سارے عمل سے کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ انھیں حکومت نے قرۃ العین حیدر کی جگہ جانے کے لیے منتخب کر لیا۔ وہ اس حق تلفی سے اس قدر دل برداشتہ اور دل شکستہ ہوئیں کہ فوراً ہی پی آئی اے سے استعفیٰ دے دیا۔ انھیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ ’’دکھ سہیں بی فاختہ اور کوے انڈے کھائیں‘‘ والی کہاوت صادق آ رہی تھی۔ پوری تفصیل ’’کار جہاں دراز ہے‘‘ میں درج ہے ۔ قرۃ العین حیدر کے ناول ہوں، ناولٹ ہوں یا افسانے پڑھنے والے کو اپنے سحر میں جکڑ لیتے ہیں البتہ ان کے رپورتاژ مجھے زیادہ متاثر نہیں کر سکے۔ اسی طرح ’’چاندنی بیگم‘‘ بھی بہت سے تضادات کا شکار ہے۔ جس کا تفصیلی ذکر میں نے اپنی کتاب ’’قرۃ العین حیدر کے افسانوں کا تجزیاتی مطالعہ‘‘ میں کیا ہے لیکن جہاں تک گردش رنگ چمن ، آگ کا دریا، آخر شب کے ہم سفر اور ’’اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو‘‘ کی بات ہے۔ تو میں کہوں گی یہ تینوں ناول ایک ایسا انسانی اور تاریخی المیہ ہیں جسے فراموش کرنا ممکن نہیں حالانکہ ’’آگ کا دریا‘‘ کے جواب میں ’’سنگم‘‘ اور ’’اداس نسلیں‘‘ لکھے گئے لیکن پڑھنے والے فرق جانتے ہیں۔ ’’آخرشب کے ہم سفر‘‘ میں سابقہ مشرقی پاکستان سانس لیتا نظر آتا ہے۔ انسانوں کی زندگی کا تضاد کس طرح ان کی شخصیت کو تبدیل کر دیتا ہے۔ ریحان الدین احمد جو کہ نام نہاد سوشلسٹ ہیں۔ کس طرح دولت ملنے کے بعد ان کی خود غرض اور کمینی فطرت سامنے آتی ہے۔ اسی طرح نواب قمر الزمان جو ریحان کے ماموں تھے۔ ان کی عالیشان ارجمند منزل میں پادری بینرجی اور الشہر بینرجی جیسے غریب اور بے وقعت میاں بیوی کی بیٹی روزی پناہ لیتی ہے۔ اور پھر ایک دن ایک بڑے آدمی سے شادی کر کے رادھیکا سانیال بن جاتی ہے۔ اپنے ماں باپ اپنے طبقے سے دغا کرتی ہے۔ دیپال سرکار جو کمیونسٹ ہے وہ بھی اپنے طبقے اور آئیڈیاز سے بغاوت کر کے اعلیٰ طبقے میں شامل ہو جاتی ہے۔ قرۃ العین حیدر نے بڑی چابک دستی اور فنکاری سے نام نہاد سوشلسٹوں کا چہرہ دکھایا ہے۔ خاص طور سے روزی اور ریحان۔ اس طرح کے کردار ہم سب نے بھٹو دور میں بہت قریب سے دیکھے ہیں۔ جب بہت سے ’’جیالوں‘‘ نے جیل کاٹی۔ پھر اسی وفاداری کا خراج وصول کر کے پاکستان سے باہر چلے گئے۔ جہاں وہ مکمل طور پر ’’عیش‘‘ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جب سال میں ایک بار پاکستان آتے ہیں۔ اور اپنی کتاب کی رونمائی نہایت تزک و احتشام سے کرتے ہیں۔ تو ان کے توانا چہروں، قیمتی لباس، انگوٹھیوں اور بیش قیمت چشموں کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ یہ تو وہی ہیں جو تھڑوں پہ سوتے تھے۔ فیس ادا کرنے کے پیسے نہیں ہوتے تھے۔ پھر ایک شارٹ کٹ دریافت ہوا’’۔۔۔۔۔ سوشلزم۔۔۔۔‘‘ اور اس ’’پارس پتھر‘‘ کو انھوں نے چوم کر جیب میں رکھ لیا اور بوقت ضرورت خوب استعمال کیا۔ اپنے پرانے ساتھیوں سے وہ اب اس طرح بات کرتے ہیں جیسے وہ کسی راجواڑے سے آئے ہوں۔ ان کی بیٹیاں دو دو ہزار کی لپ اسٹک لگاتی، جینز پہنتی نظر آتی ہیں۔ اور یہ خوشی سے پھولے نہیں سماتے کہ اصل منزل تو ان کی یہی تھی۔ دراصل دولت مندوں سے نفرت اس لیے تھی کہ خود اس سے محروم تھے۔ حسد اور جلن کی بنا پر سوشلسٹ بن گئے اور جب سوشلزم کے پارس پتھر نے انھیں بھی نو دولتیوں کی صف میں لاکھڑا کیا تو یہ سگار بھی اپنے لیڈر کے انداز میں پینے لگے۔۔۔۔!! سابقہ مشرقی پاکستان کے تناظر میں انھوں نے ایک ناولٹ بھی لکھا تھا ’’چائے کے باغ‘‘ جس میں چائے کے باغات میں کام کرنے والے مزدوروں کے مسائل سے بھری زندگی کا احاطہ کیا گیا ہے۔ ان کی ناولوں اور افسانوں کے بیشتر کردار حقیقی ہیں۔ جنھیں انھوں نے زندگی میں کہیں نہ کہیں دیکھا تھا۔ ’’نظارہ درمیاں ہے‘‘ کی ’’تارابائی‘‘ یا ۔۔۔۔’’اکثر اس طرح سے بھی رقص فغاں ہوتا ہے‘‘ کی یونی جمال آراء۔۔۔۔۔ یا ’’اگلے جنم موہے بٹیا نہ کیجیو‘‘ کی قمرن۔۔۔۔ جس کی زندگی پہ مظفر علی نے بھارت میں ’’انجمن‘‘ نامی فلم بنائی تھی۔ جو چکن کاڑھنے والی عورتوں کی زندگی پہ مبنی تھی، اس فلم میں مرکزی کردار شبانہ اعظمی نے ادا کیا تھا۔ ’’کار جہاں دراز ہے‘‘۔۔۔۔۔ کی تیسری جلد ’’شاہراہ حریر‘‘ کے نام سے شائع ہوئی ہے ۔ حصہ سوم میں انھوں نے ایک ایسی خاتون کا ذکر کیا ہے۔ جو پی ای سی۔ ایچ سوسائٹی میں اکثر ہمارے گھر آتی تھیں۔ یہ تھیں نام ور رقاصہ ’’میڈم آزوری‘‘ ۔۔۔۔ لیکن اس سوانحی ناول سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا اصلی نام کچھ اور تھا۔ وہ ماں باپ کے رکھے ہوئے نام سے ’’آزوری‘‘ کیسے بنیں ، تمام تفصیل یہاں موجود ہے۔ میڈم آزوری نرسری پہ قائم ایک اسکول ’’قائدین اسکول میں میوزک ٹیچر تھیں۔ اور بچوں کو ٹیبلو وغیرہ کی تیاری کے ساتھ ساتھ تھوڑا بہت کلاسیکی رقص بھی سکھاتی تھیں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب انتہا پسندوں نے پر امن معاشرے کو یرغمال نہیں بنایا تھا۔ میرے بھائیوں کے بچے اس اسکول میں پڑھتے تھے۔ یوں ان کی ہم سے واقفیت ہوئی تھی۔ انشاء اللہ کسی دوسرے کالم میں اس کردار سے تفصیلی ملاقات کرواؤں گی۔ اسی طرح ’’سیتا ہَرن‘‘ کی مایا کو ہم نے کراچی یونیورسٹی کے شعبہ انگریزی میں دیکھا تھا۔ دبلی پتلی سی مایا جمیل جو غالباً وہاں لیکچرر تھیں۔ خاموش اور اپنی ذات میں گم رہنے والی تھیں۔ جن لوگوں نے ’’سیتا ہَرن ‘‘ پڑھا تھا۔ اور جو انھیں جانتے تھے وہ انھیں دیکھتے ہی سرگوشیاں کرتے۔۔۔۔۔ ’’وہ دیکھو وہ مایا جمیل ہیں جن کا ذکر قرۃ العین حیدر نے کیا ہے ۔۔۔۔اور ہم سب انھیں یوں چوری چوری دیکھتے کہ کہیں وہ ہماری چوری نہ پکڑ لیں۔۔۔۔۔ پھر نجانے وہ کہاں چلی گئیں۔ بہرحال قرۃ العین حیدر ایک مکمل عہد تھیں اور ان کی وفات کے بعد اس زریں عہد کا بھی خاتمہ ہوگیا۔۔۔۔!!
1 note
·
View note
Text
سیّد رضا علی وحشتؔ کلکتوی وفات 30 جولائی
سیّد رضا علی وحشتؔ کلکتوی وفات 30 جولائی
30؍جولائی 1956 *بنگال کے غالب، اردو ادب کے استاد شاعر اور بنگال کے ممتاز مابعد کلاسیکی شاعر” سیّد رضا علی وحشتؔ کلکتوی صاحب “ کا یومِ وفات…* نام *سیّد رضا علی، وحشتؔ* تخلص۔ *۱۸؍نومبر ۱۸۸۱ء* کو *کلکتہ* میں پیدا ہوئے۔ *مدرسہ عالیہ کلکتہ* میں تعلیم پائی۔ کچھ عرصہ امپریل ریکارڈ ڈپارٹمنٹ میں چیف مولوی کے عہدے پر فائز رہے۔ بعدازاں کلکتہ میں اسلامیہ کالج میں اردو اور فارسی کے پروفیسر کی حیثیت سے خدمت…

View On WordPress
0 notes
Text
اُردو مزاح اُمید سے ہے!
منگل 23 فروری 2021ء
ڈاکٹر اشفاق احمد ورک
اکیسویں صدی میں اُردو مزاح کا تذکرہ آتے ہی ذہن میں مزاحیہ مشاعرے اور کامیڈی شو گھوم جاتے ہیں، پھر ان کے بارے میں سوچتے سوچتے دماغ بھی گھوم جاتا ہے۔ مزاح تو ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ اکثر بد مذاقوں کو مذاق بن جانے کا بھی پتہ نہیں چلتا۔ جب کہ یہاں تو یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ مزاح اور مذاق میں ’ح ، ق‘ جتنا نہیں، کوہ قاف جتنا فاصلہ ہوتا ہے۔ مزاح کی بابت ہمارا کامل ایمان ہے کہ یہ خدا کی دین ہے اور اس دین کا احوال موسیٰ سے نہیں قاری اور نقاد سے پوچھنا پڑتا ہے بلکہ یہاں باہر سے زیادہ ممد و معاون اندر کا نقاد ہوتا ہے۔
مزاح کا تھوڑا بہت عنصر ہر انسان کے اندر قدرتی طور پر موجود ہوتا ہے۔ ترکیبات، ترغیبات اور ترجیحات اس کے تخصص کا تعین کرتی ہیں۔یہ شاہیں اعلیٰ ترین ذوق اور کامل ترین ہنر کی تدبیروں سے زیرِ دام آتا ہے۔ یہ ادب اور آداب کی دنیا کا وہ واحد قرینہ ہے کہ بادشاہ سے فقیر تک جس کے لیے تشنہ کام دیکھے گئے ہیں۔ عوام و خواص میں ہر طبقۂ فکر کے لوگ اس کی زلفوں کے اسیر پائے گئے ہیں۔ یہ عزیز چونکہ گفتگو، نثر اور شاعری کی سلطنتوں پہ یکساں راج کرتا ہے، نہ صرف راج کرتا ہے بلکہ تینوں سے داد اور دھن کا خراج بھی وصول کرتا ہے۔ تاریخ کی آنکھ نے قدیم ایران کے آمروں سے لے کے موجودہ پاکستان کے ’جمہوروں‘ تک کے درباروں میں رنگ رنگ کے مسخروںکو مصاحبوں کے درجہ پہ متمکن دیکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ برے بھلے بہت سے لوگ آج بھی اس عزیزی کی رفاقت اختیار کرنے کی کاوشیں کرتے ملتے ہیں،کیونکہ ادبی اصناف اور سماجی اوصاف میں یہ ’کماؤ پُوت‘ کے نام سے معروف ہے۔
فی الحال ہم اُردو شاعری کی بات کریں گے، جس میں اس وقت دو طرح کا مزاح لکھا جا رہا ہے۔ ایک وہ جس سے ہنسی آتی ہے، دوسرا وہ جس پر ہنسی آتی ہے۔ پہلی قسم کے لوگوں میں ایک نمایاں نام ڈاکٹر بدر منیر کا ہے، جن کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ماتھے پہ لطیفہ سجا کے نہیں چلتے، دوسرے یہ کہ وہ پُرکاری کا کام اداکاری سے نہیں لیتے کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مزاح محض مسخرہ پن نہیں بلکہ نہایت سنجیدہ فعل ہے۔ڈاکٹر بدر منیر ہمارے دیرینہ دوست ہیں اور آپس کی بات ہے، وہ ظاہری وجود کے کسی بھی زاویے سے مزاح ��گار نہیں لگتے بلکہ دور سے دیکھیں تو تامل ہیرو لگتے ہیں، لیکن ان کی شاعری پڑھ کے دیکھیں تو کامل ہیرو لگتے ہیں۔ ذرا غور تو کریں کہ زیرِ نظر مثال میں انھوں نے برِ صغیر بھر کے ایک دیرینہ سماجی المیے کو شاعرِ مشرق کے نہایت سنجیدہ اور بھرپور تاریخ کے حامل شعر کے ایک مصرعے کی تضمین کے ہلکے سے ٹوِسٹ سے کیا دل فریب شگفتگی عطا کر دی ہے:
گھر میں شوہر ، اہلیہ اور ساس بھی موجود ہے
’’کیا کسی کو پھر کسی کا امتحاں مقصود ہے؟‘‘
یہ حقیقت ہے کہ شاعری لطافتیں تلاشنے کا نام ہے، اور مزاح شرارتیں تراشنے کا کام ہے۔ ڈاکٹر بدر منیر کو دونوں کی تدبیر کرنا آ تی ہے۔ اچھے مزاح نگار کا کمال ہی یہ ہوتا ہے کہ جن چیزوں کے تذکرے پر آنسو نکلنے ہوتے ہیں، وہ وہاں گدگدی کا ماحول پیدا کر دیتا ہے۔ محبوب کا تعین اور طلبی ہر آدمی کا نہایت سنجیدہ اور ذاتی مسئلہ ہوتا ہے، وہ مرنے مارنے پہ اتر سکتا ، اس پہ کسی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرتا لیکن مزاح نویس کی ادا ہی الگ ہے، ملاحظہ ہو:
مولا مِری دعا کو اتنا تو ویٹ دے دے
گر وہ نہیں تو اس کی فوٹو سٹیٹ دے دے
دنیا بھر کے اعداد و شمار مخبری کرتے ہیں کہ ازدواجی مسائل، سماج کی گھمبیرتا کا سب سے بڑا سبب ہیں۔یہ ایسا کار زار ہے کہ جہاں بڑے بڑوںکو زار زار ہی دیکھا گیا ہے۔مزاح نگار کا حوصلہ دیکھیے کہ وہ ایسے معاملات کو بھی لالہ زار بلکہ گل و گل زار کرنے کی سعی کرتا رہتا ہے۔وہ ایسے مسائل پہ جِز بِز ہونے کی بجائے ان پہ تمسخرانہ نگاہ ڈالتا ہے۔ غالب کے بارے میں کسی نقاد نے کہا تھا کہ سمجھ نہیں آتی غالب کو اتنا جدید ہونے کی جرأت کیسے ہوئی؟ جب کہ اسے اپنے زمانے میں زندہ بھی رہنا تھا۔ بعینہـٖ ہم ایسا خراج ایسے شاعروں کے لیے بھی وقف کر سکتے ہیں، جو کوہِ ازدواج سے جوئے شیرِ ظرافت نکالنے میں کامران ٹھہرتے ہیں اور جنھیں شوہر اور شاعر کی دونوں پوسٹوں پہ ایک ہی تنخواہ میں کام بھی کرنا ہوتا ہے۔ اس میدان میں ڈاکٹر بدر منیر کے تیور دیکھیے:
شادی ہو جائے تو کتنا فرق زیادہ ہو جاتا ہے
بیوی دُگنی ہو جاتی ہے ، شوہر آدھا ہو جاتا ہے
شادی سے پہلے تو ویٹ کراتی ہے
بعد میں پھر دفتر سے لیٹ کراتی ہے
شوہر ایسی سِم ہے جس کو اُس کی بیگم
جیسے چاہے ایکٹی ویٹ کراتی ہے
وجودِ زن کا حسیں فلسفہ بجا لیکن
سکوتِ زن سے ہے تصویرِ کائنات میں رنگ
عقد کے بعد بہت تھوڑی مدت میں یہ احساس ہوا
چینی مال آیا ہے جاپانی کے دھوکے میں
اس نے تو فیس بک کو ہی محبوب کر لیا
رانجھا بہت مزے سے ہے اب ہیر کے بغیر
مزاح گو شاعروں کے موضوعات بالعموم خوف ناک حد تک محدود ہوتے ہیں۔ وہ بیگم اور بکروں کے مسائل سے کم کم ہی باہر جھانکتے ہیں لیکن ڈاکٹر بدر منیر کا مشاہدہ اور موضوعات زندگی کے بے شمار پہلوؤں پر محی�� ہیں، جن پہ طبع آزمائی کرتے ہوئے وہ مزاح کا ہر معروف حربہ استعمال میں لاتے ہیں۔ تضمین، تحریف اور تلفیظ پہ انھیں خاص مہارت حاصل ہے۔ کلاسیکی ادب کے گہرے مطالعے نے بھی ان کے کلام کو وقعت عطا کر رکھی ہے۔ پھر اس سب کے ساتھ ساتھ ان کی سیاسی بصیرت بھی قابلِ داد ہے۔ مزاح کے شانہ بشانہ وہ حسبِ ضرورت طنز کی ترکیب بھی استعمال میں لاتے ہیں۔ ان جملہ اوصاف نے ان کے کلام کو رنگا رنگی کے ساتھ ہمہ رنگی سے بھی ہم کنار کر رکھا ہے۔ چند مثالیں دیکھیے:
لالچی کتے کا قصہ صرف بچے کیوں پڑھیں؟
لیڈروں کے واسطے بھی یہ سبق آموز ہو
فیس بُک پہ مادھوری ڈکشٹ کے جیسا پوز ہو
دیکھنے والا بھلا کیسے نہ لطف اندوز ہو
اس کی مہمان نوازی ہے سمجھ سے باہر
کاٹ کے آم کھلاتا ہے جو تلوار کے ساتھ
سو رہا ہے لپیٹ کر کمبل
اپنا اے سی slow نہیں کرتا
پڑا نہیں کسی گوری سے واسطہ ورنہ
زبانِ غیر سے ہم شرحِ آرزو کرتے
پیسے جو رکھ کے بھول گیا تھا دراز میں
یاد آ گئے ہیں آج اچانک نماز میں
اہلِ سیاست کہتے تھے کہ دھرتی سونا اُگلے گی
سنتے سنتے کتنی چاندی آ گئی اپنے بالوں میں
کہیں سے لائو ارینج کر کے اگر فراری ، تو میں تمھاری
کراکے شاپنگ کھلائو سجی ،مٹن، نہاری، تو میں تمھاری
کہنے لگا غریب سے سائل کو ایک پیر
کھیسے میں کچھ نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں؟
0 notes
Text
عبدالقادر حسن … کچھ یادیں کچھ باتیں
اٹھائیس نومبر کو ایکسپریس کے اسی صفحے پر چھپنے والے اپنے کالم ’’اچھا دوستو خدا حافظ‘‘ میں جب ہم سب کے عزیز عبدالقادر حسن یہ سطریں لکھ رہے تھے کون کہہ سکتا تھا کہ صرف دو دن بعد وہ خود بھی اُن دوستوں میں شامل ہو جائیں گے جنھیں خدا حافظ کہا جا رہا ہے۔ موت ایک اَٹل حقیقت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، یہ بات بھی سب کے علم میں ہے کہ ہر آنے والا دن ہماری زندگیوں سے ایک دن کم کرتا چلا جا رہا ہے اور بقول انورؔ مسعود یہ شعور بھی رکھتے ہیں کہ: وہ بھی مریں گے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ پر ایک حقیقت ہے کہ کسی بڑے مقصد کے لیے انجام کو جانتے بوجھتے ہوئے قبول کرنے والوں کے سوا کوئی بھی اس حقیقت کو خوشدلی سے قبول کرنے پر تیار نہیں ہوتا اور کم و بیش یہی واقعہ اُن لوگوں کو رخصت کرتے سمے پیش آتا ہے جو آپ کے دل سے قریب ہوں۔
عبدالقادر حسن کا صحافتی کیریئر نصف صدی سے بھی زیادہ عرصے پر پھیلا ہوا ہے اور اپنے موجودہ ’’غیر سیاسی کالم‘‘ سے قبل بھی وہ بہت سے عنوانات کے تحت کالم نگاری کر چکے ہیں لیکن اُن کی شخصیت اور صلاحیت پر بات کرنے سے قبل میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں آپ کو اُن کی اپنی وفات سے دو دن قبل لکھے گئے تعزیتی کالم کے کچھ حصے سناؤں کہ ان کی معرفت خود انھیں سمجھنے میں آسانی ہو گی۔ ’’جو لوگ چلے جاتے ہیں اُن کے لیے ہمارے پاس اس کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا کہ ہم بچشمِ نم اُن کے لیے دعائے مغفرت کریں انھیں اچھے الفاظ میں یاد کریں اور اُن سے وابستہ یادوں کو تازہ کریں۔ گزشتہ دنوں میرے چند ایسے کرم فرما ہمیں بھٹکتا چھوڑ کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے پہلے میرے مہربان اُردو ڈائجسٹ کے بانی ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی چلے گئے اُن کے پیچھے ہمارے اسلام آبادی شاہ جی سید سعود ساحر روانہ ہوئے۔ ان دونوں کا غم ابھی تازہ تھا کہ چوہدری انور عزیز چلے گئے۔ صحافت کی زندگی میں ان اصحاب سے میرا خاص تعلق رہا۔
ڈاکٹر اعجاز حسن قریشی اُردو ڈائجسٹ کے بانی ایڈیٹر بھی تھے اور اُن کی رہنمائی میں اخبار نویسوں کی جو کھیپ تیار ہوئی وہ آج تک صحافت پر حکمرانی کر رہی ہے …… جب کبھی ایمان ڈولنے لگتا ہے تو یہ لکیریں دیوار بن کر سامنے آ جاتی ہیں ان لوگوں کے مقابلے میں ہم آج کے صحافی رئیس ہیں اور اپنی حیثیت میں زندہ رہ سکتے ہیں لیکن بدقسمتی سے ایمان سلامت نہیں رہے ہماری خوش حالی ہمارے ایمان کو کھا گئی۔ شائد یہی وجہ ہے کہ ہماری تحریروں میں برکت نہیں رہی حرفِ مطبوعہ کی عزت باقی نہیں رہی اور اس کے ساتھ ہماری عزت بھی، مجھے تعزیتیں لکھنا نہیں آتیں شائد اس لیے کہ زندوں کی تعزیت اور عزاداری سے فرصت ملے تو کوئی اس دنیا سے آنے جانے والوں کو یاد کرے اور آنسو بہائے مگر بعض ایسے لوگ بھی ہم سے رخصت ہو جاتے ہیں کہ جن کے اُٹھ جانے کے بعد ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے ہیں وہ اپنے پیچھے محاورتاً اور رسماً نہیں واقعتاً خلاء چھوڑ جاتے ہیں ایک ہولناک خلا جس میں ڈر لگتا ہے تنہائی اور بڑھ جاتی ہے۔
انسان اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرنے لگتا ہے کسی ایسے آدمی کے چلے جانے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاں قحط الرجال کس قدر خوفناک ہوتا جا رہا ہے کہ ہم ہمیشہ اپنے آپ کو نعم البدل سے محروم محسوس کرتے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے جیسے ہمیں کچھ اچھے لوگ کوٹے میں ملے تھے اور اب ہمارا کوٹا ختم ہو گیا ہے ۔ کوئی سوسائٹی روپے پیسے کی کمی سے دیوالیہ یا فقیر نہیں ہوتی بلکہ اس سے تو بگڑتی ہے وہ ایسے لوگوں سے محروم ہو کر ادھوری اور فاقہ زدہ ہو جاتی ہے جو اس میں آبِ حیات بن کر زندہ رہتے ہیں اور اعلیٰ روایات کے خزانے لُٹاتے رہے اور یہ آبِ حیات اور یہ خزانے اُن کے آنکھیں بند کرتے ہی خشک اور خالی ہو گئے‘‘ اس معیار کے پسِ منظر میں دیکھا جائے تو عبدالقادر حسن خود بھی اس صف کے آدمی تھے ان سے تعلقِ خاطر قائم ہونے کی بنیادی وجہ تو احمد ندیم قاسمی مرحوم تھے کہ نہ صرف دونوں کا آبائی علاقہ ایک تھا بلکہ اُن میں محبت اور احترام کا وہ رشتہ بھی ساری عمر برقرار رہا جو کبھی ہمارے دیہاتی سماج کا طرہّ امتیاز ہوا کرتا تھا۔
ایکسپریس اخبار کے اس ادارتی صفحے پر یکجا ہونے کے علاوہ میرا اُن کا ساتھ محبت اور احترام کے باوجود زیادہ تر تعلق رسمی نوعیت کا رہا کہ میں تیس سال مسلسل کالم لکھنے کے باوجود اپنی دیگر مشغولیات کے باعث صحافی برادری کا باقاعدہ حصہ نہ بن سکا جب کہ وہ اس کے پرچم برداروں میں سے تھے۔ اتفاق کی بات ہے کہ گزشتہ دس پندرہ برس میں اُن سے زیادہ اُن کے فرزندِ ارجمند اطہر حسن سے ملاقات رہی کہ وہ پی آئی اے کے شعبہ تعلقات عامہ کا سینئر افسر ہے ا ور اس بہانے اُس سے ملاقات کا موقع نکلتا رہتا ہے۔ عبدالقادر حسن کلاسیکی انداز میں لکھنے والے کالم نگار تھے یعنی اُن کے کالم میں نیم فکاہیہ انداز میں سیاست، ادب، معاشرتی اقدار اور ملکی اور بین الاقوامی خبروں کو موضوع بنایا جاتا تھا، ایک حد سے زیادہ تیزی نہ اُن کے مزاج میں تھی نہ قلم میں، وہ اُن لوگوں میں سے تھے جو مسکراہٹ کو صدقہ سمجھ کر ہمہ وقت اسے تقسیم کرتے رہتے ہیں اور اپنی تحریر میں لوگوں کی دل آزاری کے بجائے مفاہمت اور درگزر سے کام لیتے تھے۔
اس میانہ روی کی اُن کو قیمت دینا پڑی کہ آج کل کی جذباتی وابستگی اور مخالف کی دلیل کے صحیح حصے کو بھی تسلیم نہ کرنے کی روش نے بہت سے کالم نگاروں کو بھی سیاسی ورکر کی سطح پر لا کھڑا کیا ہے اور ایسا نہ کرنے والوں کی صلح جوئی کو ان کی کمزوری سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان کے اس آخری کالم ’’اچھا دوستو خدا حافظ‘‘ میں ایک ساتھ تین نامور مرحومین کا ذکر کیا گیا ہے، میرے علم میں نہیں کہ ان میں سے کورونا کسی کی رحلت کا باعث بنا یا نہیں، بوجوہ میں عبدالقادر حسن کی نماز جنازہ میں بھی شامل نہیں ہو سکا (جس کا بہت افسوس ہے) سو یہ بھی علم نہیں کہ خود عبدالقادر حسن اس سے متاثر تھے یا نہیں لیکن جس کثرت اور تیزی سے ان دنوں احباب رخصت ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ پر ایک خوفناک تجربہ اور احساس ہے کہ کم از کم میری ہوش میں یہ واحد موقع ہے (اور اللہ کرے آخری ہو) کہ گزشتہ کئی ماہ سے روزانہ اخبارات کے صفحات اور فیس بُک پر کسی نہ کسی ایسے شخص کی کورونا زدگی یا اس کے باعث رحلت کی خبر ملتی ہے جس کا تعلق آپ کی زندگی کے کسی نہ کسی رشتے سے ہوتا ہے، سو اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیئے۔
آخر میں عبدالقادر حسن کے لیے مغفرت کی دعا کے ساتھ اُن کے ایک کالم سے اقتباس جو اُن کے اندازِ تحریر کا ایک خوبصورت نمونہ بھی ہے۔ ’’ہم یہ مانیں یا نہ مانیں یہ ایک اَٹل حقیقت ہے کہ ہمارے ملک میں ہر طرف رشوت کا بازار گرم ہے۔ جائز کام کروانے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ ایک وقت تھا اس ملک میں رشوت چُھپ کر لی جاتی تھی اور عمومی طور پر اسے بُرا سمجھا جاتا تھا اور اگر کسی شخص کے بارے میں یہ پتہ ہوتا تھا کہ وہ راشی ہے تو اُس کے محلے دار اور رشتے دار اُس سے بات کرنا پسند نہیں کرتے تھے اور وہ خاندان کی تقاریب میں بھی دوسرے لوگوں سے الگ تھلگ رہتا تھا۔ شائد آپ کو یہ باتیں آج قصے کہانیاں لگیں لیکن اگر آپ ایک لمحے کے لیے اپنے ذہن کے دریچوں کو ٹٹولیے تو شاید آپ کو یہ سب باتیں یاد آ جائیں گی، دیکھیے کیسے دھیرے دھیرے پورا معاشرہ اور اُس کی اقدار سب کچھ بدل گیا اور ہمیں خبر بھی نہ ہوئی یا شاید ہم خبر رکھنا ہی نہیں چاہتے تھے‘‘
امجد اسلام امجد
بشکریہ ایکسپریس نیوز
0 notes
Text
اصغر مال کالج : جسم کا رؤاں رؤاں اس درسگاہ کا شکر گزار ہے
اس کالم کی پہلی قسط ڈاکٹر شاہد صدیقی نے دو تین دن پہلے انہی صفحات پر لکھی‘ گویا دبستاں کھول دیا ع بلبلیں سن کر مرے نالے غزل خواں ہو گئیں گورنمنٹ کالج اصغر مال میری بھی مادر درسگاہ (Alma Mater) ہے۔ اس کے درودیوار میرے بھی دل پر نقش ہیں۔ دو سال جو وہاں گزرے‘ ڈھاکہ یونیورسٹی میں گزارے گئے عرصہ کے بعد‘ عمر کے بہترین دو سال ہیں۔ سترہ سال کا تھا جب بی اے کے لیے اس عظیم الشان دارالعلم میں داخل ہوا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب درسگاہیں ��اقعی درسگاہیں تھیں۔علم بھی بٹتا تھا تربیت بھی دی جاتی تھی۔ تعلیمی ادارے ابھی یرغمال نہیں بنے تھے۔ تقاریب میں اہلِ سیاست نہیں اہلِ علم تشریف لاتے تھے۔ اس کالج میں حفیظ جالندھری کے ہاتھوں سے انعام حاصل کیا۔ قادرالکلام شاعر‘ معرکہ آرا شعری مجموعے‘‘ ہفت کشور'' کے مصنف جعفر طاہر کو پہلی اور آخری بار یہیں دیکھا۔ وہ کچھ کچھ سیہ فام تھے۔ سٹیج پر جہاں وہ کھڑے تھے‘ ان کے پیچھے کالے رنگ کا پردہ تھا۔ طلبہ نے شور مچایا کہ جعفر طاہر نظر نہیں آرہے اس لیے پیچھے سے کالے رنگ کا پردہ ہٹایا جائے۔ ڈاکٹر کنیز فاطمہ یوسف کے‘ جو قائد اعظم یونیورسٹی میں تھیں‘ لیکچر یہیں سنے۔ کیا تقریر ہوتی تھی ان کی شستہ انگریزی میں‘ دریا کی روانی کے مانند !
اس زمانے کے دو بہترین ماہرینِ تعلیم ہمارے پرنسپل رہے۔ پروفیسر اشفاق علی خان اور ڈاکٹر سید صفدر حسین ! پروفیسر اشفاق علی خان کو کون نہیں جانتا۔ الحمزہ کے نام سے برسوں انگریزی کالم لکھتے رہے۔ سٹیل انڈسٹری قائم کرنے کے بہت بڑے مبلغ تھے اور سول سروس کے ناقد۔ ہمیں ان کی ایک تلقین یہ بھی ہوتی تھی کہ جوتے صاف رکھا کرو۔ ان کے صاحبزادے کامران علی خان اسی کالج میں میرے کلاس فیلو تھے۔ سی ایس ایس کر کے انفارمیشن سروس میں آئے۔ شاید میرے بیچ میٹ تھے۔ اس زمانے میں کامن ٹریننگ نہیں تھی اور ہر گروپ کی تربیت الگ الگ ہوتی تھی۔ عجیب اتفاق ہے کہ کالج چھوڑنے کے بعد آج تک کامران سے ملاقات نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر سید صفدر حسین شاعر بھی تھے۔ معرّا نظم کہتے تھے۔ نظم سنانے کا انداز ان کا خاص تھا۔ محفل پر چھا جاتے تھے۔ نظموں کے کئی مجموعے تھے جن میں ''رقص ِطاؤس‘‘ بہت مشہور ہوا۔ پروفیسر اقبال بخت ہمارے اکنامکس کے پروفیسر تھے۔ ہمیشہ سفید براق پتلون شرٹ میں ملبوس۔
یہاں یہ ذکر بھی ہو جائے کہ اُس عہد میں کالجوں کے اساتذہ خوش لباس ہوتے تھے اور اس حوالے سے طلبہ کے آئیڈیل ! بہترین سوٹ میں ملبوس۔ اور گرما میں بہترین قمیض اور پینٹ! برسوں بعد اسی اپنے کالج میں ایک پروفیسر دوست کے ساتھ گیا۔ سٹاف روم میں اساتذہ کی ہیئت کذائی اور لباس کا انداز دیکھا تو دم گھٹنے لگا۔ بغیر استری کے شلوار قمیضیں ! اکثر نے واسکٹ نہیں پہنی ہوئی تھی اور کچھ کے پیروں میں چپلیں تھیں۔ پروفیسر سجاد حیدر ملک ہمیں انگریزی شاعری اور ڈراما پڑھاتے تھے۔ ادب کا ذوق رکھتے تھے اور پڑھاتے ہوئے مسحور کر دیتے تھے۔ میں اکثر انہیں کسی گوشے میں بیٹھ کر ٹائم یا نیوزویک میگزین پڑھتے دیکھتا۔ غالبا وہ اُس زمانے کے بڑے انگریزی روزنامے ''پاکستان ٹائمز‘‘ میں بھی کام کرتے تھے۔ ہماری خوش قسمتی یہ تھی کہ کلاسیکی انگریزی شاعری کی جگہ جدید شاعری کورس میں رکھی گئی تھی۔ اس کتاب کا نام تھا An Anthology of Modern English Verse۔ اس میں ٹی ایس ایلیٹ سے لے کر رالف ہاجسن تک سب نئے شعرا تھے۔ ساٹھ میں سے اکثر نظمیں زبانی یاد ہو گئی تھیں۔ استادِ مکرم پروفیسر سجاد حیدر سیٹلائٹ ٹاؤن راولپنڈی میں مقیم ہیں۔
دوست عزیز شاہد مسعود ملک نے از راہ کرم ان کا ایڈریس اور فون نمبر عطا کیا۔ پروفیسر صاحب سے بات کی تو آواز سے ان کی صحت اچھی لگ رہی تھی۔ فرمانے لگے : آج کل خط لکھنے کا رواج نہیں رہا‘ تم مجھے خط لکھو۔ انگریزی ہی کے شعبے میں پروفیسر نذیر بھی تھے۔ سرخ گلابی رنگ کا چہرہ۔ ایک باکمال استاد! پھر وہ نئی نئی اٹھتی ہوئی پیپلز پارٹی کی نذر ہو گئے اور ایک دن ہم نے سنا کہ وفاقی وزیر خورشید حسن میر کے سیکرٹری تعینات ہو گئے۔ کہاں پروفیسری کی بادشاہی اور بلند باعزت مقام اور کہاں دربار کی ملازمت‘ مگر اُن کا اپنا نقطہ نظر تھا! بہت کم اداروں میں ایم اے کی کلاسیں تھیں‘ مگر ہمارے کالج میں اُس زمانے میں تین مضامین میں ایم اے کرایا جا رہا تھا۔ جغرافیہ‘ ریاضی اور اکنامکس۔ ادبی اور ثقافتی سرگرمیاں باقاعدگی سے منعقد ہوتی تھیں۔ کالج میگزین '' کوہسار‘‘ کے نام سے شائع ہوتا تھا۔ حصۂ اردو کا ایڈیٹر مجھے مقرر کیا گیا۔ بزم ِادب فعال تھی۔ ہم اس میں اپنی تازہ کہی ہوئی غزلیں اور نظمیں سناتے جن پر باقاعدہ تنقید کی جاتی۔
کالج میں اکثر مشاعرے ہوتے۔ ملک بھر کے تعلیمی اداروں کے مشاعروں میں اپنے کالج کی نمائندگی کی۔ اسلامیہ کالج لاہور کے شہرہ آفاق'' شمع تاثیر‘‘ کے مشاعرے سے بھی اپنے کالج کے نام پر انعام حاصل کیا۔ انہی دنوں کالج کینٹین پر بیٹھے تھے کہ کسی طالب علم نے بتایا کہ ظفر اقبال کا نیا شعری مجموعہ '' گلافتاب‘‘ چھپا ہے اور چھپتے ہی ازحد متنازعہ ہو گیا ہے۔ فوراً حاصل کیا اور سوائے آخری حصے کے جو '' مشکل‘‘ ہے باقی سارا حفظ ہو گیا۔ یہ ظفراقبال سے طویل تعلق اور عقیدت کی یک طرفہ ابتدا تھی۔ پھر وہ دن بھی آیا کہ انہوں نے کُلبۂ احزاں کو قیام سے مشرف کیا اور اس بے بضاعت کو حکم دیا کہ '' آبِ رواں‘‘ کے نئے ایڈیشن کے لیے فلیپ لکھوں۔ اس حکم کی تعمیل ہوئی۔ حافظہ خوب شعر پسند تھا۔ کالج کے دورانیہ میں احمد ندیم قاسمی کی ''دشتِ وفا‘‘، ناصر کاظمی کی'' برگِ نے‘‘، مجید امجد کی'' شب ِرفتہ‘‘ اور فراز کی ''درد آشوب‘‘ مکمل کی مکمل حفظ تھیں۔ عدم اور جوش کے بھی بے شمار اشعار یاد تھے۔ یوسف ظفر کے صاحبزادے نوید ظفر مرحوم ( جو بعد میں پی ٹی وی میں اعلیٰ مناصب پر رہے ) ایک سال سینئر تھے۔ ایک دن کہنے لگے کہ کالج لائبریری میں انہیں اپنے والد کی فلاں کتاب نہیں ملی۔ پوچھا‘ کون سی نظم کی ضرورت پڑ گئی؟ بتایا تو وہ نظم انہیں زبانی سنا دی !
پھر امتحان ہوا اور کالج سے جدائی کا مرحلہ آیا۔ ڈر تھا کہ فیل نہ ہو جاؤں۔ نتیجہ آیا تو کالج میں پہلی پوزیشن تھی۔ رول آف آنر بھی ملا۔ کچھ برسوں بعد کالج جانا ہوا تو مین ہال میں دیواروں پر سال بہ سال رول آف آنر لینے والوں کے نام آویزاں دیکھے۔ صرف 1967 ء والی جگہ خالی تھی کہ اُس سال میں نے لیا تھا بقول ناصر کاظمی ؎
کتنی مردم شناس ہے دنیا منحرف بے حیا ہمیں سے ہوئی
ایم اے اکنامکس کے لیے داخلہ اصغر مال کالج ہی میں لیا۔ پروفیسر اصغری شریف صدر شعبہ تھیں۔ مجموعی ( ایگریگیٹ ) نمبروں کی بنیاد پر پنجاب یونیورسٹی کا سکالرشپ بھی ہو گیا۔ اسی اثنا میں مشرقی پاکستان کے لیے بین الصوبائی فیلو شپ کا مقابلہ ہوا۔ خوش بختی سے ڈھاکہ یونیورسٹی کے شعبہ اقتصادیات کی نشست مل گئی۔ یہ ایک نئی دنیا تھی۔ اڑھائی تین سال وہاں گزارنے اور پورا مشرقی بنگال دیکھنے کا فائدہ یہ ہوا کہ آج مشرقی پاکستان کی علیحدگی کے اصل عوامل سے بخوبی آگاہی ہے۔ اور یہ جو ہر سال سولہ دسمبر کو بھانت بھانت کے نام نہاد تجزیے نظر آتے ہیں ان کا کھوکھلا پن واضح ہے۔ اصغر مال کالج کے کلاس روم اور چھلکتے برآمدے آج بھی دل میں آباد ہیں ! جسم کا رؤاں رؤاں اس درسگاہ کا شکر گزار ہے۔ اس کی لائبریری کے بے پناہ احسانات ہیں۔ اس کے اساتذہ میرے لیے مقدس ہیں۔
شاد باد اے عشق خوش سودائی ما
محمد اظہارالحق
بشکریہ دنیا نیوز
0 notes
Text
سیمیں خان درانی
آہ سیمیں خان درانی——-ہمارے معاشرے کاسب سے بڑا المیہ اس کی منافقت ہے – مغربی معاشرے میں منافقت نہیں ہے اس لیے ان کے مسائل ہمارے مسائل جیسے نہیں ہیں -کہنے کو تو پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن یہاں اسلامی نظام کی جگہ انگریز کا بنایا ہوا عدالتی نظام رائج ہے -اور جمہوریت کی جگہ سول مارشل لاء نے لے رکھی ہے – اس معاشرے میں کسی عورت کا عورت ہونا ایک بڑا جرم ہے – اور اگر عورت لکھاری ہے تو پھر تو…
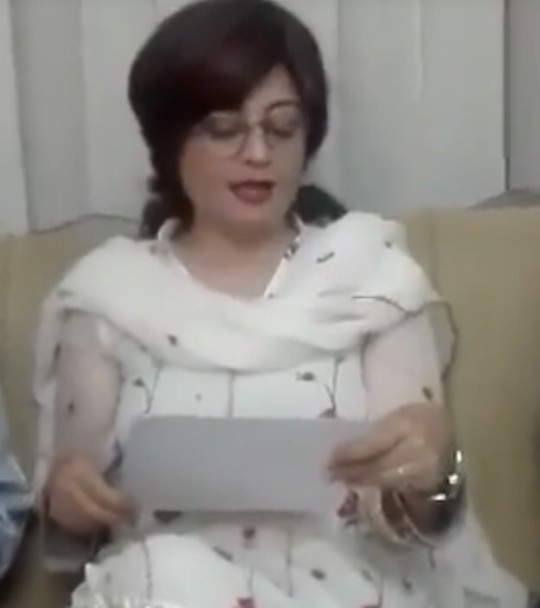
View On WordPress
#Khabrain Manchester newspaper#Nadia umber Lodhi editor#Parveen Shakir poetess by Nadia Umber Lodhi poetess#مضامین#نادیہ عنبر لودھی کی شاعری اور نثر#کلاسیکی ادب#اردو شاعرات#طنز ومزاح
0 notes
Text

جدید مختصر کہانیوں کا ماسٹر ۔
گا ئے ڈی موپاساں
تحریر ۔ فراز احمد
گائے ڈی موپاساں 5 اگست 1850کوپیداہوا اور 6 جولائی 1893ا کو دنیا سے رخصت ہو گیا، 19 ویں صدی اس فرانسیسی مصنف اور مختصر کہانیوں کے ماسٹر کے بغیر ادھوری ہے،مو پاساں کو جدید مختصر کہانیوں کا باپ کہا جاتا ہے،وہ صرف 42سال زند ہ رہا، مگر ایسے ایسے شاہکار تخلیق کیے جس نے فرانسیسی ادب کو بلندیوں کے آسمان پر پہنچا دیا،بعد میں آنے والے سبھی مصنفین نے اس کی ذہنی صلاحیتوں کا نہ صر ف اعتراف کیا بلکہ غیر ارادی طور پر اس کے نقش قدم پر چلنے کی بھی کوشش کی،موپاساں کو نیچر کے نمائندے کے طور پر بھی یاد کیا جاتا ہے، اس کی کہانیوں میں ، فطرت پسندی ، حقیقت پسندی ، انسانی زندگیاں ، تقدیر، مایوسی ، بے بسی،بھوک ، افلاس ،جنگ، معاشرتی قوتجا بجا بکھری دکھائی دیتی ہے،موپاساں نہ صرف شاعر ، ناول نگاربھی تھا، مگرمختصر کہانیوں نے اسے زندہ جاوید کر دیا ۔
موپاساں کی کہانیوں میں 1870 کی فرانکو پرشین جنگ ، شہریوں پر گزرے واقعات ، حادثات و تجربات صاف دکھائی دیتے ہیں ، موپاساں نے 300 مختصر کہانیاں ، چھ ناول ، تین سفری کتابیں ، اور آیت کا ایک جلد تحریر کیا ۔ ان کی پہلی شاءع شدہ کہانی ، ;34; بولے ڈی سوف گیند آف پسینے جسے شاہکار کا درجہ دیا جاتا ہے ۔
موپاساں جب گیارہ سال کا تھا تو اس کی والدہ جو کہ آزاد سوچ کی حامل تھیں ، نے اپنے شوہر سے قانونی الگ ہو گئیں ، علیحدگی کے بعد ، وہ خود کلاسیکی ادب خصوصا شیکسپیئر کو بہت پسند کرتی تھی ۔ تیرہ سال کی عمر تک موپاساں خوشی سے اپنی والدہ کے ساتھ ، اٹریٹ میں ، ولا ڈیس ورگوئس میں رہائش پذیر رہا ، جہاں ، سمندر اور پرتعیش دیہی علاقے موجود تھے ، ، اسے ماہی گیری اور بیرونی سرگرمیوں کا بہت شوق تھا ۔ تیرہ سال کی عمر میں ،اس کی ماں نے اسے اور اس کے بھائی کو کو روئین کے ایک نجی اسکول میں داخل کرا دیا،موپاساں نے اسی سال کالج سے گریجویشن کیا جس سال فرانکو پرشین جنگ ہوئی ،اس نے جنگ میں ایک رضاکار کی حیثیت حصہ لیا ۔ بعد ازاں 1871 میں ، وہ نارمنڈی چھوڑ کر پیرس چلا گیا جہاں انہوں نے بحریہ کے محکمہ میں کلرک کی حیثیت سے دس سال گزارے ۔
موپاساں کے لکھاری بننے میں گوسٹاو فلو برٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے،جس نے نہ صرف اس کی رہنمائی کی ، اور اسے دنیا کا سب سے بڑا مصنف بنا دیا، گوسٹاو فلوبرٹ نے موپاساں کی صحافت اور ادب میں رہنمائی کرتے ہوئے ادبی سرپرست کی ، موپاساں نے فلوبرٹ کے گھر پر ایمائل زولا اور روسی ناول نگار ایوان تورگینیف کے ساتھ ساتھ حقیقت پسندی اور فطرت پسند اسکولوں کے بہت سارے حامیوں سے بھی ملاقات کی ۔ اور ذہن کی تعمیرکی ۔ 1878 میں موپاساں لی فگارو ، گل بلاس ، لی گالوئس اور لچو ڈی پیرس جیسے متعدد مشہور اخبارات میں معاون ایڈیٹر بن گیا ۔ انہوں نے اپنا فارغ وقت ناول اور مختصر کہانیاں لکھنے میں صرف کیا ۔
1880 میں پہلا ناول بولے ڈی صوف منظر عام پر آیا، جس نے فوری اور زبردست کامیابی حاصل کی ۔ فلاوَبرٹ نے اسے ;;ایک شاہکار جو برداشت کرے گا کے طور پر پیش کیا ۔ فرانسیہ پرشین جنگ کے دوران یہ ماوَساسنٹ کا مختصر افسانوں کا پہلا ٹکڑا تھا ،پھرڈیوکس امیس مدر سیویج ، دی ہیکل اور میڈیموسیل فیفی جیسی مختصر کہانیاں بھی سامنے آئیں ۔ 1880سے 1891 موپاساں کی زندگی کا سب سے زرخیز دور تھا ۔ 1881 میں موپاساں نے لا میسن ٹیلئر کے عنوان سے مختصر کہانیوں کا پہلا جلد شاءع کیا ۔ جو صرف دو سال کے اندر اندر اپنے بارہویں ایڈیشن تک پہنچ گیا ۔ 1883 میں ، اس نے اپنا پہلا ناول اون واء (انگریزی میں ایک عورت کی زندگی کے طور پر ترجمہ کیا جس کی ایک سال میں پچیس ہزار کاپیاں فروخت ہوئیں ، دوسرا ناول بیل امی ، 1885 میں سامنے آیا ، جسے چار مہینوں میں سینتیس بار چھاپا گیا ۔ موپاساں کاسب سے زیادہ پاسند کیا جانے والا مختصر افسانہ ، دی ہار، دی نکلیس ہے جس میں ایک محنت کش طبقے کی لڑکی کہانی بیان کی گئی ہے جو ایک اعلی معاشرتی پارٹی میں شرکت کے کے لیے ایک دولت مند دوست سے ہار لیتے ادھار لیتی ہے اور کھو بیٹھتی ہے ۔ بعد ازاں پوری زندگی ہار کی رقم کی ادائیگی کرتی ہے، پھر آخری میں پتہ چلتا ہے کہ یہ ہار اصلی نہیں ، بلکہ نکلی تھا، اور اس کی محنت بے فائدہ رہی
1890 میں موپاساں سیفلیس نامی بیماری کا زشکار ہو گیا، جو اس کی ذہنی بیماری کا باعث بنی،جو وقت کے ��اتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی،ماپاساں کی کہانیوں میں چند ایک جگہ جنونی کی��یت بھی نظر آتی ہیں ،جو شاید ان کی بیماری کی علامت کے طور پر ہوں ،کچھ نقادوں نے بھی ان کی کہانیوں کے موضوعات کو انکی نشوونما پذیر ذہنی بیماری کا نقشہ بتا کر پیش کیا ۔ لیکن ڈی موپاسنٹ کا ہارر افسانہ ان کے کام کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ ہے ، جو سب سے الگ اور منفرد ہے، جس کا موازنہ اسٹیفن کنگ کے مشہور ناول دی شائننگ سے کیا جا سکتا ہے ۔ موپاساں ذہنی کیفیت و جنون میں اپنا گلا کاٹ کر خودکشی کرنے بھی کوشش کی جو اس کے دماغی جنونی کیفیت کو ظاہر کرتی ہے،انہوں نے
اپنی زندگی کے آخری 18 ماہ پیرس کے ایک ذہنی علاج کے ادارے ڈاکٹر ایسریپٹ بلانچ کے مشہور نجی سیاسی پناہ میں گزارے اور وہیں 6جولائی 1893 میں ان کا انتقال ہو گیا ۔
3 notes
·
View notes
Text
پاکستانی اردو شاعری
پاکستانی اردو شاعری اور جدید اردو شاعری کا نقطہ آغاز تقریباً ایک ہی ہے۔ جدید اردو شاعری کو جن شعراء نے بنیاد فراہم کی اُن میں حالی اور آزاد نمایاں ہیں اور دونوں کے ہاں ملی شاعری کے نمونے بھی مل جاتے ہیں، خصوصاً مسدسِ حالی کو اردو ملی شاعری اور مسلمان قوم کی شاعری میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ بعد میں اردو شاعری تحریکِ آزادی کی آبیاری کرنے میں بہت مدد گار بن گئی۔ یہاں علامہ اقبال اور مولانا ظفر علی خان نمایاں حیثیت کے شاعر ہیں۔ قیامِ پاکستان کے بعد وہ شعراء جنھوں نے قومی شاعری کا منظر نامہ تشکیل دیا ان میں سے کافی پہلے ہی درخشاں ستارے بن چکے تھے۔ ان میں غزل گو شعراء بھی تھے اور نظم لکھنے والے بھی۔ غزل گو شعراء میں ناصر کاظمی، شہزاد احمد اور سلیم احمد کے نام بہت اہم ہیں جب کہ نظم گو شعراء میں ن م راشد، منیر نیازی، میرا جی ، حفیظ جالندھری، فیض احمد فیض، مختار صدیقی اور احمد ندیم قاسمی کو بہت پذیرائی ملی۔
قیامِ پاکستان کے بعد اردو شعر و ادب میں تقسیمِ برصغیرِ کے نتیجے میں ہ��رت اور اس کے دکھ کے آثار و اثرات نمایاں طور پر سامنے آئے۔ شاعری میں بچھڑے ہوئے عزیزوں اور چھوڑے ہوئے گھر بار کی یاد، اس کا کرب اور لُٹی پُٹی زندگی کے آثار دکھائی دیے اور اس کے ساتھ ہی استعارتی metaphorical سطح پر خواب اور سفر کے استعارے تشکیل پائے۔ خواب کا استعارہ روشن زندگی کی تڑپ سے پیدا ہوا اور سفر اس کی عملی تعبیر کی جانب اشارہ کرتا ہے۔ یہ دونوں استعارے اپنی صورت بدلتے ہوئے آج کی شاعری میں بھی کہیں نہ کہیں دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان استعاروں کی معنویت وقت کے ساتھ بدلتی ضرور رہتی ہے لیکن اب نصف صدی سے زائد عرصہ میں انھیں مستقل استعاروں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ پاکستان کی تہذیبی، ثقافتی، سیاسی، معاشی اور معاشرتی تمام صورتِ حال کو ان استعاروں کے تجزیاتی مطالعہ Analytical study سے سمجھا جا سکتا ہے۔ اس لحاظ سے اردو شاعری نے اپنے معاشرے کی ایک متوازی تاریخ ان استعاروں میں مستور کر رکھی ہے۔
یہاں تک آتے آتے پاکستانی اردو شاعری اپنا ارتقائی سفر طے کرتی ہوئی اس مقام تک پہنچتی ہے جہاں علامہ اقبال کے بعد راشد، میرا جی اور مجید امجد جیسے بڑے شاعر بہت حد تک اپنا کام مکمل کر چکے تھے۔ ان کی شاعری کے پسِ منظر میں رومانوی تحریک، ترقی پسند تحریک اور حلقہ اربابِ ذوق نے فعال کردار انجام دیا خصوصاً حلقہ اربابِ ذوق نے جدید غزل کے اسلوب کی تشکیل میں اور جدید نظم کے ہیئتی formative اور اسلوبی stylistic ارتقا میں نمایاں خدمات انجام دیں۔ جدید نظم میں بلینک ورس Blank verse وآزاد نظم کی ہیئتوں کے علاوہ پابند نظم کے متنوع تجربات ظہور پذیر ہوئے۔
سنہ 1960 کی دہائی میں جدیدیت کی تحریک کے زیرِ اثر موضوعاتی (Thematic) حوالے سے وجودیت کے فلسفے اور فنی حوالے سے علامت نگاری کے اثرات اردو شاعری پر مرتب ہوئے جس کی وجہ سے ایک تخلیقی ابہام (creative vagueness) پیدا ہوا۔ جس نے نئی شاعری کی معنوی وسعت میں اضافہ کیا۔ جیلانی کامران جیسے شعرا کی لسانی تشکیلات linguistic construction اور ��ئی شاعری کی تحریکوں نے اردو شاعری میں گراں قدر اضافے کیے اور اس کا لسانی دائرہ وسیع کیا۔ نئی لفظیات، نئے استعارے اور نئی علامات نے جدید صنعتی معاشرت اور شہری زندگی کے اظہار کو ممکن بنایا۔ اسی دور میں نثری نظم کے لیے کوششیں شروع ہوئیں جنھیں ابتدا میں پذیرائی نہیں ملی بلکہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ شدو مد سے رد کیا گیا۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ ہی نئے تجربات کے خلاف شور برپا ہوتا رہا ہے۔ بلینک ورس اور نثری نظم کے خلاف طوفان کم و بیش دو دہائیوں تک برپا رہا لیکن آخرِ کار مخالفت دم توڑ گئی۔
اگرچہ جدیدیت کے متوازی خالص ترقی پسند شاعری کا دھارا بھی مسلسل رواں دواں دکھائی دیتا ہے اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دور کی پاکستانی شاعری ایک خالص انسانی معاشرے کے خواب پر مشتمل نظر آتی ہے۔ اس دور کے اکثر شعراء فارم یعنی ہیئتی حوالے سے وسیع سوچ رکھتے تھے۔ بہت کم شاعر ایسے ہیں جنھوں نے محض غزل یا محض نظم پر اکتفا کیا ہو ورنہ بیشتر شاعروں کے ہاں نئی پابند ہیئتیں، بلینک ورس نظمیں، آزاد نظمیں اور کہیں کہیں نثری نظمیں بھی مل جاتی ہیں۔ مجید امجد، منیر نیازی،احمد ندیم قاسمی، مصطفیٰ زیدی، حبیب جالب اور سرمد صہبائی سمیت اور بہت سے شعراء نے فارم میں تنوع کو پیشِ نظر رکھا۔ صرف ظفر اقبال ہی ایک ایسا شاعر ہے جس نے غزل کے علاوہ کسی اور صنفِ ادب کو اختیار نہیں کیا۔ نظم کے شعراء میں پروفیسر جیلانی کامران، انیس ناگی عباس اطہر اور اختر حُسین جعفری کے نام اہمیت رکھتے ہیں۔
اردو شاعری کا اگلا دور فارم کی نسبت اسلوب کے تنوع کا دور ہے۔ اس دور میں ایک طرف کلاسیکی اسلوب کی جھلکیاں صاف دکھائی دیتی ہیں تو دوسری طرف داستانوی اسلوب کو اختیار کرنے والے شاعروں کا بھی ایک پورا قبیلہ نظر آتا ہے۔فکری طور پر وجودیت کے اثرات اس دور کی شاعری پر زیادہ گہرے ہیں لیکن سیاسی و سماجی شعور کا اظہار بھی زیادہ تخلیقی انداز میں ہوا ہے۔ اس دور میں مسلمانوں کے گم گشتہ تہذیبی ورثے کی بازیافت کا عمل استعاروں کی صورت میں نظر آتا ہے جو اس عہد کے سیاسی منظر نامے کو بہترین شکل میں پیش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کنیزیں، لشکر، گھوڑا، تلوار اور قرطبہ جیسے استعارے صرف ایک نئی شعری روایت ہی نہیں تشکیل دے رہے تھے بلکہ اپنے عہد کے معاملات و مسائل کی پیش کش کے لیے مناسب ترین تھے۔
اس دور کے شاعروں میں شبیر شاہد، ثروت حسین، اظہارالحق اور افضال احمد سید کے نام اہم ہیں۔ ان شاعروں نے اپنی تخلیقی کاوشوں سے خالص پاکستانی ادب کی فضا دریافت کی۔ ایسے شعراء کی ایک خصوصیت یہ بھی تھی کہ یہ سارے ہی قیامِ پاکستان کے بعد آزاد فضا میں پیدا ہوئے یوں دیکھا جائے تو خالص پاکستانی شعراء کی یہ پہلی نسل تھی جس نے اپنی کوششوں سے وہ فضا بنائی جو موجودہ دور پر منتج ہوئی۔ موجودہ اردو شاعری کا دور 1977 سے شروع ہوتا دکھائی دیتا ہے۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ دور جنرل ضیاالحق کے استبدادی اور مارشل لائی دور سے شروع ہوتا ہے۔ یہ دور سیاسی حوالے سے جبر اور معاشی حوالے سے اس سرمایہ داری کا حامل ہے جس نے صارفیت Consumerism کو پیدا کیا اور جس کے نتائج نیو ورلڈ آرڈر اور گلوبلا ئیزیشن کی صورت میں برآمد ہوئے۔ اس دور میں اردو شاعری فطری طور پر احتجاجی رنگ میں ظہور پذیر ہوئی۔
ایک اچھی بات اس دور کی یہ ہے کہ بلا تخصیص دائیں اور بائیں بازو سے تعلق رکھنے والے سبھی شاعر اس میں شریک تھے۔ جدید اردو شاعری کے سو سالہ سفر کے دوران ہیئت، اسلوب اور موضوع کے جو جو تجربات ہوئے اور جتنے اضافے ہوئے، اس دور تک آتے آتے وہ سارے ایک نامیاتی کُل میں ڈھل گئے، غیر ضروری عناصر جھڑ گئے اور طاقت ور عناصر سے پاکستانی شاعری کی نئی روایت پیدا ہوئی۔ اس دور کے شاعروں نے تجربات کے بجائے شعریت کو اہمیت دی۔ لمبے ارتقائی سفر نے انھیں جو کچھ سکھایا وہ اپنی بہترین شکل میں شعری قالب اختیار کر گیا۔
اس دور سے تعلق رکھنے والے بیشتر شاعر اب تک اپنے تخلیقی امکانات کی دریافت میں مصروفِ عمل ہیں اگرچہ اس دور میں کوئی شاعر ایسا نظر نہیں آتا جسے اقبال ، فیض اور ن م راشد کے بعد عظیم شعری روایت و تجربے کا امین کہا جا سکے لیکن مجموعی طور پر شاعری کا ایک بڑا ذخیرہ غزل اور نظم کی تمام اصناف میں جمع ہو گیا ہے۔ ان دنوں وبا کی لپیٹ میں پاکستان سمیت ساری دنیا آئی ہوئی ہے۔ یہ ایک ایسا تجربہ ہے جس سے ہماری کئی نسلیں پہلی دفعہ متاثر ہوئی ہیں۔ ہمارے شعرا ء بھی اس سے متاثر ہوئے ہیں ۔ توقع کی جا سکتی ہے کہ یہ تجربہ ایک نئی شعری روایت کو جنم دے گا۔ نئے استعارے وجود پذیر ہوں گے اور شعری اسلوب کے نئے دھارے پھوٹیں گے۔
عبد الحمید
بشکریہ ایکسپریس نیوز
4 notes
·
View notes
Text
اردو ادب ۱۸۵۷ تا ۱۹۱۴
اردو ادب پر مغربی اثرات انیسویں صدی کے آغاز سے ہی پڑنے لگے تھے۔ مگر ان کا فیصلہ کن اثر ۱۸۵۷ء کے بعد ہوا۔ فورٹ ولیم کالج کی سادہ نثر، دہلی کالج میں درسی کتابوں کے لیے مفید اور واضح انداز بیان، ماسٹر رام چندر کے مضامین اور مرزا غالب کے خطوط میں یہ اثرات دیکھے جا سکتے ہیں۔ شاعری کا تعلق روایت سے زیادہ ہوتا ہے۔ اس لیے ۱۸۵۷ء سے پہلے کی شاعری میں صرف غالب کے یہاں تشکیک، ارضیت اور انفرادیت کے نقوش ایک ایسے ذہن کے آئینہ دار ہیں جو روایت کے ساتھ نئے امکانات اور میلانات پر بھی نظر رکھتا ہے۔ ادب سیاسی تبدیلیوں کا یکسر تابع نہیں ہوتا، نہ ادبی ارتقا کی منزلیں سیاسی بنیاد پر متعین کی جا سکتی ہیں۔ مگر زمانے اور مزاج کی تبدیلیوں کا اثر ادب پر بہرحال پڑتا ہے۔
اسی لیے ۱۸۵۷ء سے جب انگریزوں کے الفاظ میں غدر ہوا اور برصغیر مورخوں کے الفاظ پہلی جنگ آزادی لڑی گئی، اردو ادب کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کے ادب کو سہولت کے لیے کلاسیکی اور اس کے بعد کے ادب کو جدید کہا جا سکتا ہے۔ مگر اس کے معنی یہ نہیں لینا چاہئیں کہ ۱۸۵۷ء کے بعد کلاسیکی اثرات ختم ہو گئے۔ کلاسیکی یا روایتی ادب کا سلسلہ جاری رہا۔ مگر جدید فکرو فن جو پہلے تجربے کے طور پر شروع ہوا، رفتہ رفتہ اپنی جگہ بناتا گیا یہاں تک کہ انیسویں صدی کے آخر تک نئے میلانات حاوی ہو گئے۔
ہمارا کلاسیکی ادب مجموعی طور پر ازمنہ وسطیٰ کی قدروں کا نمائندہ ہے۔ اس کی بنیاد برصغیر کی سرزمین ہے مگر اس میں عجم کے حسنِ طبیعت کے بہت سے رنگ شامل ہیں۔ اس میں نمایاں فکر تصوف س�� آئی ہے۔ اور اس کے نقش و نگار اس مشترک تہذیب سے لیے گئے ہیں جو تاریخی اسباب کی بنا پر پروان چڑھ رہی تھی۔ اس کی شاعری میں تخیل کی پرواز ملتی ہے اور فطرت، تہذیب اور سماج کی مص��ری بھی۔ صوفیوں کے اثر سے اس میں ایک انسان دوستی آئی اور دربار نے اسے ایک رنگینی اور صنّاعی سکھائی۔ اس دور میں نثر پر توجہ کم ہوئی اور زیادہ تر یہ راہِ نجات یا داستان سرائی کے لیے ہی استعمال ہوئی اور شاعری سے آرائش کے لیے زیور لیتی رہی۔
فورٹ ولیم کی جدید نثر تفریحاً نہیں فرمائش پر لکھی گئی تھی۔ اس میں قصے کہانیوں کا سرمایہ زیادہ تھا۔ دہلی کالج میں درسی ضروریات کے لیے علمی نثر بھی وجود میں آئی، صحافت رفتہ رفتہ قدیم اسلوب سے آزاد ہوئی اور کارآمد اور عام فہم ہونے لگی۔ مغرب کے معلم، مشنری اور منتظم سب یورپ کے اٹھارویں صدی کے ادب سے متاثر تھے۔ اسی لیے مغربی اثرات شروع شروع میں وہاں کے نوکلاسیکی ادب کی قدروں کے مظہر تھے۔ انہیں کی رہنمائی میں ہمارے یہاں جدید ادب حقیقت نگاری کا علم بردار بن کر سامنے آیا۔ ناول کی تاریخ میں نذیر احمد کے بعد رتن ناتھ سرشار کی اہمیت ہے (۱۸۴۶ء۔ ۱۹۰۲ء ) سرشار کے یہاں رجب علی سرور کے فسانہ عجائب کا رنگ بھی ہے اور مکالمات میں لکھنؤ کی بیگماتی زبان کی بے تکلفی بھی۔
سرشار کا فسانہ آزاد سب سے پہلے قسط وار منشی نول کشور کے اودھ اخبار میں نکلا، بعد میں یہ کتابی صورت میں چھپا۔ فسانہ آزاد میں اصل قصہ گویا ایک کھونٹی ہے جس پر ہزاروں واقعات ٹنگے ہوئے ہیں۔ سرشار ہندوستانی نشاۃ الثانیہ سے متاثر تھے اور نئے خیالات کے حامی تھے۔ مگر لکھنؤ کی تہذیب کے عاشق۔ پہلی جلد کے آخر میں انہوں نے لکھا ہے کہ ’’میاں آزاد کا ہر شہرو دیار میں جانا اور وہاں کی بری رسموں پر جھلّانا‘‘ ناول کا عمدہ پلاٹ ہے۔ انہوں نے پرانے خیالات اور رسم و رواج پر اپنی شوخی و ظرافت سے خوب خوب وار کیے ہیں۔ ان کا ہیرو آزاد ایک مثالی کردار ہے جو مردانہ حسن کے ساتھ سپہ گری میں بھی طاق ہے اور علم و ادب کا رسیا بھی ’’فسانہ آزاد‘‘ چار ضخیم جلدوں میں ہے۔
مگر آج اس کی اپیل زیادہ تر بیگمات کے مکالموں یا خوجی کے کردار کی وجہ سے ہے۔ ’’فسانہ آزاد‘‘ کے علاوہ سرشار کا ’’سیر کہسار‘‘ بھی لکھنؤ کی نوابی معاشرت پر گہرا طنز ہے۔ سرشار کے دوسرے ناول چنداں اہمیت نہیں رکھتے۔ سرشار کے یہاں ناہمواری ہے اور ضبط و نظم کی کمی ہے مگر ان کی خلاقی، ان کی مرقع نگاری، کرداروں اور کارٹونوں کی ایک دنیا ایک تندرست اور کہیں کہیں بے رحم ظرافت اور زبان پر قدرت کو تسلیم کرنا ضروری ہے۔ اس دور میں اردو کی پہلی جامع لغت ’’فرہنگ آصفیہ‘‘ کے نام سے لکھی گئی۔ مولوی سید احمد دہلوی (۱۸۴۶ء۔ ۱۹۲۰ء ) نے چوبیس سال کی محنت کے بعد ۱۸۹۲ء میں چار جلدوں میں یہ لغت شائع کی۔
اس سے پہلے وہ ’’ارمغان دہلی‘‘ کے نام سے اس کا ایک حصہ شائع کر چکے تھے۔ اس لغت کی تیاری میں انہیں ڈاکٹر ایس ڈبلیو فیلن کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کی وجہ سے خاصی مدد ملی۔ ڈاکٹر فیلن کی ’’ہندوستانی انگریزی لغت‘‘ ۱۸۷۹ء میں شائع ہو گئی تھی۔ فرہنگ آصفیہ میں اگرچہ جا بجا مؤلف نے غیر ضروری باتیں بیان کی ہیں اور بعض غیر مصدقہ روایات پر تکیہ کیا ہے ، پھر بھی یہ لغت اور بعد کی مولوی نورالحسن نیّر کا کوروی کی ’’نور اللغات‘‘ اب تک اردو کی سب سے اچھی لغات میں سے سمجھی جاتی ہیں۔ گو لغت نویسی کے جدید معیار کے لحاظ سے دونوں میں خامیاں ہیں۔ امیر مینائی کی ’’امیر اللغات‘‘ اگر چہ صرف الف مقصورہ تک ہی ہے مگر قابلِ قدر ہے۔ ۱۸۵۷۔ ۱۹۱۴ کا دور ہر لحاظ سے اردو ادب کا زرّیں دور ہے۔
کلاسیکی طرز کی شاعری کے علاوہ اس دور میں نظمِ جدید کا آغاز ہوا اور اس نے نمایاں ترقی کی اور موضوعات اور ہئیت دونوں کے لحاظ سے اردو شاعری کا دامن وسیع ہوا۔ مگر دراصل یہ دور نثر کی ترقی اور وسعت کا دور ہے۔ سرسید احمد خان کی تحریک کے اثر سے نثر علمی مضامین کے اظہار پر قادر ہوئی۔ ۱۹۱۴ء میں جب حالی اور شبلی کا انتقال ہوا تو شاعری کی بساط پر حسرت موہانی کے ساتھ علامہ اقبالؒ کا نام لیا جانے لگا اور پریم چند نے اپنے افسانے لکھنے شروع کر دیئے تھے۔ ابوالکلام آزاد کا ’’الہلال‘‘ افقِ صحافت پر طلوع ہو چکا تھا۔ سجاد حیدر کے ساتھ لطیف الدین احمد اکبر آبادی اور نیاز فتح پوری، ادب لطیف کی بنیادیں مضبوط کر رہے تھے۔
اردو ادب اب اپنے پیرو پر کھڑا تھا اور اسے مذہبی یا سیاسی بیساکھیوں کی ضرورت نہ رہی تھی۔ وہ مذہب اور سیاست سے کام لیتا تھا۔ مگر ان کا غلام نہ رہا تھا۔ اس دور کے ان شعرا میں جنہوں نے نئی شاعری کو وقعت اور بلندی عطا کی ان میں نادر کاکوروی اور درگاسہائے سرور جہاں آبادی کا نام لینا بھی ضروری ہے۔ نادر کاکوروی (۱۸۵۷ء۔ ۱۹۱۲ء ) اپنے ہم عصر ادیبوں میں انگریزی ادب سے زیادہ واقف تھے۔ انہوں نے آزاد اور حالی کی نیچرل شاعری کی لے کو آگے بڑھایا۔ سادگی اور واقعیت ان کی شاعری کی خصوصیات ہیں۔ ان کا کلام ’’جذباتِ نادر‘‘ کے نام سے دو حصوں میں شائع ہوا۔ انہوں نے کئی انگریزی نظموں کے کامیاب ترجمے کیے اور ان کی طبع زاد نظموں میں بھی انگریزی شاعری کا اثر جھلکتا ہے۔ ان کا کارنامہ ٹامس مور کی نظم ’’لالہ رخ‘‘ کے ایک قصے کا ترجمہ ہے۔ ’’مخزن‘‘ میں ان کا کلام برابر چھپتا تھا اور اقبالؒ نے ان کی اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔
محمد ریاض
1 note
·
View note
Photo

ظ ۔ انصاری ۔۔۔ راشد جاوید احمد ظل حسنین انصاری ( ظ۔انصاری) تحقیق ۔۔ راشد جاوید احمد کے کلاسیکی لڑیچر کے اردو تراجم پڑھنے والوں کے لئے ڈاکٹر ۔ظ۔ انصاری کا نام روسی زبان کے کلاسیکی لڑیچر کے اردو تراجم پڑھنے والوں کے لئے نامانوس نہیں ۔ سوویت عہد میں روسی زبان کے ایک درجن سے زائد کلاسیکی ناولوں اور شاعری کا اردو ترجمہ ظ ۔ انصاری نے کیا تھا ۔ ظ۔ انصاری روسی شعر و ادب کاترجمہ براہ راست روسی سے اردو میں کیا کرتے تھے اور یہ ایک ایسا کام تھا جو اُن سے پہلے کسی اردو ادیب نے نہیں کیا تھا ۔
0 notes
Text
انتخاب نیر مسعود ۔۔۔ ترتیب: اجمل کمال
انتخاب نیر مسعود ۔۔۔ ترتیب: اجمل کمال
انتخاب نیر مسعود
نیر مسعود
ترتیب: اجمل کمال
ڈاؤن لوڈ کریں
ورڈ فائل
ای پب فائل
کنڈل فائل
تعارف
’’16نومبر1936 تاریخ پیدائش ہے (بہ مقام ’’ادبستان‘‘لکھنؤ)، ادبی تربیت والد مرحوم پروفیسر سیّد مسعود حسن رضوی ادیب کے زیر سایہ ہوئی۔ گھر کے کتب خانے میں کلاسیکی ادب کی کتابیں تھیں۔ مکان سے متصل الطاف فاطمہ صاحبہ کا مکان تھا، ان کے یہاں بچوں کے رسالے…
View On WordPress
1 note
·
View note
Text
ایک باپ بکاؤ ہے افسانہ راجندر سنگھ بیدی

دیکھی نہ سنی یہ بات جو ۴۲ فروری کے ’’ٹائمز‘‘ میں چھپی۔ یہ بھی نہیں معلوم کہ اخبار والوں نے کیسے چھاپ دی۔خرید و فروخت کے کالم میں یہ اپنی نوعیت کا پہلا ہ�� اشتہار تھاجس نے وہ اشتہار دیا تھا ارادہ کے بغیر اسے معمے کی ایک شکل دے دی تھی۔پتے کے سوا اس میں کوئی ایسی بات نہ تھی جس سے خریدنے والے کو کوئی دلچسپی ہو۔بکاؤ ہے ایک باپ۔عمر اکہتر سال۔بدن اکہرا،رنگ گندمی،دمے کا مریض حوالہ نمبر ایل۶۷۴۔معرفت ٹائمز۔ اکہتر برس کی عمر میں باپ کہاں رہا....دادا نانا ہو گیا۔وہ تو؟عمر بھر آدمی ہاں ہاں کرتا رہتا ہے۔آخر میں نانا ہو جاتا ہے۔ باپ خرید لائے تو ماں کیا کہے گی،جو بیوہ ہے عجیب بات ہے نا۔ایسے ماں باپ جو میاں بیوی نہ ہوں۔ ایک آدمی نے الٹے پاؤں دنیا کا سفر شروع کر دیا ہے آج کی دنیا میں سب سچ ہے بھائی۔سب سچ ہے۔ دمہ پھیلا دے گا۔ نہیں بے۔دمہ متعدی بیماری نہیں۔ ہے۔ نہیں۔ ہے۔ ان دونوں آدمیوں میں چاقو چل گئے۔جو بھی اس اشتہار کو پڑھتے تھے۔بڈھے کی سنک پرہنس دیتے تھے۔پڑھنے کے بعد اسے ایک طرف رکھ دیتے اور پھر اٹھا کر اسے پڑھنے لگتے۔جیسے ہی انہیں اپنا آپ احمق معلوم ہونے لگتا وہ اشتہار کو اڑوسیوں پڑوسیوں کی ناک لگے ٹھونس دیتے۔ ایک بات ہے....گھر میں چوری نہیں ہو گی۔ کیسے؟ ہاں کوئی رات بھر کھانستا رہے۔ یہ سب سازش ہے۔خواب آور گولیاں بیچنے والوں کی۔ پھر....ایک باپ بکاؤ ہے! لوگ ہنستے ہنستے رونے کے قریب پہنچ گئے۔ گھروں میں،راستوں پر،دفتروں میں بات ڈاک ہونے لگی۔جس سے وہ اشتہار اور بھی مشتہر ہو گیا۔ جنوری فروری کے مہینے بالعموم پت جھڑ کے ہو تے ہیں۔ ایک ایک داروغے کے نیچے بیس بیس جھاڑ دینے والے سڑکوں پر گرے سوکھے،سڑے بوڑھے پتے اٹھاتے اٹھاتے تھک جاتے ہیں۔جنہیں ان کو گھر لے جانے کی بھی اجازت نہیں ہوتی کہ انہیں جلائیں اور سردی کے موسم میں وہ اشتہار گرمی پیدا کرنے لگا جو آہستہ آہستہ سینک میں بدل گئی۔ کوئی بات تو ہو گی؟ ہوسکتا ہے،پیسے،جائیداد والا.... بکواس....ایسے میں بکاؤ لکھتا؟ مشکل سے اپنے باپ سے خلاصی پائی ہے۔باپ کیا تھا۔چنگیز ہلاکو تھا سالا۔ تم نے پڑھا مسز گو سوامی؟ دھت۔ہم بچے پالیں گے،سدھا،کہ باپ؟ایک اپنے ہی وہ کم ہیں نہیں۔گو سوامی ہے۔ باپ بھی حرامی ہوتے ہیں .... باکس ایل۶۷۴میں چٹھیوں کا طومار آیا پڑا ہے۔اس میں ایک ایسی بھی چٹھی آئی جس میں تھی کیرل کی لڑکی مس راونی کرشنن نے لکھا تھا کہ وہ ابو دبئی میں نرس کا کام کرتی رہی ہے اور اس کے ایک بچہ ہے۔وہ کسی ایسے مرد کے ساتھ شادی کی متمنی ہے جس کی آمدنی معقول ہو اور اس کے بچے کی مناسب دیکھ بھال کر سکے چا ہے وہ کتنی ہی عمر کا ہو۔اس کا کوئی شوہر ہو گا جس نے اسے چھوڑ دیا۔یا ویسے ابو دبئی کے کسی شیخ نے اسے الٹا پلٹا دیا۔چنانچہ غیر متعلق ہونے کی وجہ سے وہ عرضی ایک طرف رکھ دی گئی۔کیونکہ اس کا بکاؤ باپ سے کوئی تعلق نہ تھا۔بہرحال ان چٹھیوں سے یوں معلوم ہوتا تھا جیسے ہیڈ لے چیز،رابن سن،ارونگ اور اگا تھا کرسٹی کے سب پڑھنے والے ادھر پلٹ پڑے ہیں۔کلاسی فائڈ اشتہار چھاپنے والوں نے جنرل مینیجر کو تجویز پیش کی کہ اشتہاروں کے نرخ بڑھا دیے جائیں۔مگر نوجوان بوڑھے یا جوان مینیجر نے تجویز کو پھاڑ کر ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہوئے کہاSHUICKS ایک پاپولر اشتہار کی وجہ سے نرخ کیسے بڑھا دیں؟....اس کے انداز سے معلوم ہوتا تھا جیسے وہ کسی غلطی کا ازالہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ پولیس پہونچی۔اس نے دیکھا ہندو کالونی،دادر میں گاندھرو داس جس نے اشتہار دیا تھا،موجود ہے اور صاف کہتا ہے کہ میں بکنا چاہتا ہوں اگر اس میں کوئی قانونی رنجش ہے تو بتائیے۔وہ پان پر پان چباتا اور ادھر ادھر دیواروں پر تھوکتا جا رہا تھا۔مزید تفتیش سے پتہ چلا کہ گاندھرو داس ایک گائیک ہے۔کسی زمانے میں جس کی گائیکی کی بڑی دھوم تھی۔برسوں پہلے اس کی بیوی کی موت ہو گئی،جس کے ساتھ اس کی ایک منٹ نہ پٹتی تھی۔دونوں میاں بیوی ایک اندھی محبت میں بندھے ایک دوسرے کو چھوڑتے ہی نہ تھے۔شام کو گاندھرو داس کا ٹھیک آٹھ بجے گھر پہنچنا ضروری تھا۔ایک دوسرے کے ساتھ کوئی لین دین نہ رہ جانے کے باوجود یہ احساس ضروری تھا کہ....وہ ہے گاندھروداس کی تان اڑتی ہی صرف اس لئے تھی کی دمینتی اس کے سنگیت سے بھرپور نفرت کرنے والی بیوی گھر میں موجود ہے اور اندر کہیں گاجر کا حلوہ بنا رہی ہے اور دمینتی کے لئے یہ احساس تسلی بخش تھا کہ اس کا مرد جو برسوں سے اسے نہیں بلاتا۔ساتھ کے بستر پر پڑا،شراب میں بد مست خراٹے لے رہا ہے۔کیونکہ خراٹا ہی ایک موسیقی تھا۔جسے گاندھرو کی بیوی سمجھ پائی تھی بیوی کے چلے جانے کے بعد گاندھرو داس کو بیوی کی وہ سب زیادتیاں بھول گئیں۔ لیکن اپنے اس پر کئے ہوئے اتیا چار یاد ر ہ گئے۔وہ بیچ رات کے ایکا یک اٹھ جاتا اور گریبان پھاڑ کر ادھر ادھر بھاگنے لگتا۔بیوی کے بارے میں آخری خواب اس نے دیکھا کہ دوسری عورت کو دیکھتے ہی اس کی بیوی نے واویلا مچا دیا ہے اور روتی چلاتی ہوئی گھر سے بھاگ نکلی۔گاندھرو داس اس کے پیچھے دوڑا۔لکڑی کی سیڑھی کے نیچے کچی زمین میں دمینتی نے اپنے آپ کو دفن کر لیا۔مگر مٹی ہل رہی تھی اور اس میں دراڑیں چلی آئی تھیں جس کا مطلب تھا کہ ابھی اس میں سانس باقی ہے۔حواس باختگی میں گاندھرو داس نے اپنی عورت کو مٹی کے نیچے سے نکالا تو دیکھا ....اس کے،بیوی کے دونوں بازو غائب تھے۔ناف سے نیچے بدن نہیں تھا۔اس پر بھی وہ اپنے ٹھنٹ اپنے پتی کے گرد ڈالے اس سے چمٹ گئی اور گاندھروداس اسی پتلے سے پیار کرتا ہوااسے سیڑھیوں سے اوپر لے آیا۔گاندھروداس کا گانا بند ہو گیا۔ گاندھروداس کے تین بچے تھے۔تھے۔ کیا۔ہیں۔سب سے بڑا ایک نامی پلے بیک سنگر ہے جس کے لانگ پلیئنگ ریکارڈ بازار میں آتے ہی ہاتھوں ہاتھ بک جاتے ہیں۔ایرانی ریستورانوں میں رکھے ہوئے جیوک باکسوں سے ��تنی فرمائشیں اس کے گانوں کی ہوتی ہیں اور کسی کی نہیں۔اس کے برعکس گاندھرو داس کی کلاسیکی میوزک کو کوئی بھی گھاس نہ ڈالتا تھا۔دوسرا لڑکا آفسٹ پرنٹر ہے اور جست کی پلیٹیں بھی بنا تا ہے۔پریس سے دو ڈیڑھ ہزار روپیہ مہینہ پاتا ہے اور اپنی اطالوی بیوی کیساتھ رنگ رلیاں مناتا ہے۔کوئی جئے یا مرے اسے اس بات کا خیال نہیں۔جس زمانے میں گاندھروداس کا موسیقی کے ساز بیچنے کا کام ٹھپ ہوا تو بیٹا بھی تھا۔گاندھرو نے کہا.... چلو ایچ ایم وی کے ریکارڈوں کی ایجنسی لیتے ہیں۔چھوٹے نے جواب دیا۔ہاں مگر آپ کیساتھ میرا کیا مستقبل ہے۔گاندھروداس کو دھچکہ سا لگا وہ بیٹے کا مستقبل کیا بنا سکتا تھا؟کوئی کسی کا مستقبل کیا بنا سکتا ہے؟ گاندھرو کا مطلب تھا۔میں کھاتا ہوں تم بھی کھاؤ۔میں بھوکا مرتا ہوں تم بھی مرو۔تم جوان ہو،تم میں حالات سے لڑنے کی طاقت زیادہ ہے اس کے جواب کے بعد گاندھروداس ہمیشہ کے لئے چپ ہو گیا۔رہی بیٹی تو وہ ایک اچھے مارواڑی گھر میں بیاہی گئی۔جب وہ تینوں بہن بھائی ملتے تو اپنے باپ کو رنڈوا،مرد بدھوا کہتے اور اپنی اس اختراع سے خود ہی ہنسنے لگتے۔ ایسا کیوں؟ چانزک،ایک شاعر اور اکاؤنٹنٹ جو اس اشتہار کے سلسلے میں گاندھروداس کے ہاں گیا تھا۔کہہ رہا تھا ....اس بڈھے میں ضرور کوئی خرابی ہے۔ورنہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تین اولادوں میں سے ایک بھی اس کی دیکھ بھال نہ کرے۔کیا وہ ایک دوسرے کے اتنے نزدیک تھے کہ دور ہو گئے؟ہندسوں میں اُلجھے رہنے کی وجہ سے چانزک کے الہام اور الفاظ کے درمیان کوئی فساد پیدا ہو گیا تھا۔ وہ یہ جانتا تھا کہ ہندوستان تو کیا دنیا بھر میں کنبے کا تصور ٹوٹتا جا رہا ہے۔بڑوں کا ادب ایک فیوڈل بات ہو کر رہ گئی ہے۔ اس لئے سب بڈھے ہا ئیڈ پارک میں بیٹھےَ امتداد زمانہ کی سردی سے ٹھٹھرے ہوئے، ہر آنے جانے والے کو شکار کرتے ہیں کہ شاید ان سے کوئی بات کرے۔ وہ یہودی ہیں جنہیں کوئی ہٹلر ایک ایک کر کے گیس چیمبر میں دھکیلتا جا رہا ہے۔ مگر دھکیلنے سے پہلے جمور کے ساتھ ان کے دانت نکال لیتا ہے جن پر سونا مڑھا ہے۔ یا اگر کوئی بچ گیا تو کوئی بھانجا بھتیجا اتفاقیہ طور پر اس بڈھے کو دیکھنے کے لئے اس کے مخروطی اٹیک میں پہنچ جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہ تو مرا پڑا ہے اور اس کی کلزاقی آنکھیں اب بھی دروازے پر لگی ہیں۔نیچے کی منزل والے بدستور اپنا اخبار بیچنے کا کاروبار کر رہے ہیں کیونکہ دنیا میں روز کوئی نہ کوئی واقعہ تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ڈاکٹر آ کر تصدیق کرتا ہے کہ بڈھے کو مرے ہوئے پندرہ دن ہو گئے۔ صرف سردی کی وجہ سے لاش گلی سڑی نہیں۔ پھر وہ بھانجا یا بھتیجا کمیٹی کو خبر کر کے منظر سے ٹل جاتا ہے، مبادا کہ آخری رسوم کے اخراجات اسے دینے پڑیں۔ ًً چانزک نے کہا ....ہو سکتا ہے بڈھے نے کوئی اندوختہ رکھنے کی بجائے اپنا سب کچھ ہی بچوں پر اڑا دیا ہو۔اندوختہ ہی ایک بولی ہے جسے دنیا کے لوگ سمجھتے ہیں اور ان سے زیادہ اپنے سگے سمبندھی اپنے ہی بچے بالے۔کوئی سنگیت میں تارے توڑ لائے۔نقاشی میں کمال دکھا جائے اس سے انہیں کوئی مطلب نہیں پھر اولاد ہمیشہ یہی چاہتی ہے کہ اس کا باپ وہی کرے جس سے وہ اولاد خوش ہو۔باپ کی خوشی کس بات میں ہے۔اس کی کوئی بات ہی نہیں اور ہمیشہ نہ خوش رہنے کے لئے اپنے کوئی سا بھی بے گانا بہانہ تراش لیتے ہیں۔ مگر گاندھرو داس تو بڑا ہنس مکھ آدمی ہے۔ ہر وقت لطیفے سناتا ہے۔ خود ہنستا ہے اور دوسروں کو ہنساتا رہتا ہے۔ اس کے لطیفے اکثر فحش ہوتے ہیں شاید وہ کوئی نقاب کھو ٹے میں جن کے پیچھے وہ اپنی جنسی ناکامیوں اور نا آسودگیوں کو چھپاتا رہتا ہے یا پھر سیدھی سی بات.... بڑھاپے میں انسان ویسے ہی ٹھرکی ہو جاتا ہے اور اپنی حقیقی یا مفروضہ فتوحات کی باز گشت! اشتہار کے سلسلے میں آنے والے کچھ لوگ اس لئے بھی بدک گئے کہ گاندھرو داس پر پچپن ہزار کا قرض بھی تھا جو بات اس نے اشتہار میں نہیں لکھی تھی اور غالباً اس کی عیاری کا ثبوت تھی۔اس پر طرہ ایک نوجوان لڑکی سے آشنائی تھی جو عمر میں اس کی بیٹی رما سے بھی چھوٹی تھی۔وہ لڑکی دیویانی گانا سیکھنا چاہتی تھی جو گورو جی نے دن رات ایک کر کے اسے سکھایا اور سنگیت کی دنیا کے شکھر پر پہنچا دیا۔لیکن ان کی عمروں کے فرق کے باوجود ان کے تعلقات میں جو ہیجانی کیفیت تھی اسے دوسرے تو ایک طرف خود وہ بھی نہ سمجھ سکتے تھے۔اب بھلا ایسے چاروں عیب شرعی باپ کو کون خریدے؟ اور پھر ....جو ہر وقت کھانستا رہے کسی وقت بھی دم اُلٹ جائے اس کا۔باہر جائے تو نو ٹانک مار کے آئے،بلکہ لوٹتے وقت پوا بھی دھوتی میں چھپا کر لے آئے۔ آخر....دمے کے مریض کی عمر بہت لمبی ہوتی ہے۔ گاندھرو داس سنگیت سکھاتے ہوئے یہ بھی کہہ اٹھتا میں پھر گاؤں گا۔وہ تکرار کے ساتھ یہ بات شاید اس لئے بھی کہتا کہ اسے خود بھی اس میں یقین نہ تھا۔وہ سرمہ لگاتا بھی تو اسے اپنے سامنے اپنی مرحوم بیوی کی روح دکھائی دیتی جیسے کہہ رہی ہو۔ابھی تک گا رہے ہو؟ اس انوکھے مطالبے اور امتزاج کی وجہ سے لوگ گاندھرو داس کی طرف یوں دیکھتے تھے جیسے وہ کوئی بہت چمکتی ہوئی شے ہو اور جس کا نقش وہاں سے ٹل جانے کے بعد بھی کافی عرصے تک آنکھ کے اندر پردے پر برقرار رہے اور اس وقت تک پیچھا نہ چھوڑے جب تک کوئی دوسرا عنصر نظارہ پہلے کو دھندلا نہ دے۔ کسی خورشید عالم نے کہا....میں خرید نے کو تیار ہوں بشرطیکہ آپ مسلمان ہو جائیں۔ مسلمان تو میں ہوں ہی۔ کیسے؟ میرا ایمان خدا پر مسلم ہے۔پھر میں نے جو پایا ہے اُستاد علاؤالدین کے گھرانے سے پایا ہے۔ آں ہاں،وہ مسلمان،کلمے والا.... کلمہ تو سانس ہے انسان کی جو اس کے اندر،باہر جاری اور ساری ہے۔میرا دین سنگیت ہے۔کیا استاد عبدالکریم خان کا بابا ہرداس ہونا ضروری تھا؟ پھر میاں خورشید عالم کا پتہ نہیں چلا۔ وہ تین عورتیں بھی آئیں لیکن گاندھرو داس جس نے زندگی کو نو ٹانک بنا کے پی لیا تھا،بولا ....جو تم کہتی ہو میں اس سے اُلٹ چاہتا ہوں۔کوئی نیا تجربہ جس سے بدن ��و جائے اور روح جاگ اٹھے اسے کرنے کی تم میں کوئی ہمت ہی نہیں۔دین دھرم معاشرہ نہ جانے کن کن چیزوں کی آڑ لیتی ہو لیکن بدن روح کو شکنجے میں کس کے یوں سامنے پھینک دیتا ہے۔تم پلنگ کے نیچے کے مرد سے ڈرتی ہو اور اسے ہی چاہتی ہو تم ایسی کنواریاں ہو جو اپنے دماغ میں عفت ہی کی رٹ سے اپنی عصمت لٹواتی ہواور وہ بھی بے مہار....اور پھر گاندھرو داس نے ایک شیطانی مسکراہٹ سے کہا۔دراصل تمہارے نتیجے ہی غلط ہیں۔ ان عورتوں کو یقین ہو گیا کہ وہ ازلی مائیں دراصل باپ ہیں۔ کسی خدا کے بیٹے کی تلاش میں ہیں ورنہ تین تین چار چار تو ان کے اپنے بیٹے ہیں مجاز کی اس دنیا میں .... میں اس دن کی بات کرتا ہوں جس دن مان گنگا کے مندر سے بھگوان کی مورتی چوری ہوئی اس دن پت جھڑ بہار پر تھی،مندر کا پورا احاطہ سوکھے سڑے،بوڑھے پتوں سے بھر گیا۔کہیں شام کو بارش کا ایک چھینٹا پڑا اور چوری سے پہلے مندر کی مورتیوں پر پروانوں نے اتنی ہی فراوانی سے قربانی دی جس فراوانی سے قدرت انہیں پیدا کرتی اور پھر انہیں کھاد بناتی ہے یہ وہی دن تھاجس دن پجاری نے پہلے بھگوان کرشن کی رادھا (جو عمر میں اپنے عاشق سے بڑی تھی)کی طرف دیکھا اور پھر مسکرا کر مہترانی چھبو کی طرف (جو عمر میں پجاری کی بیٹی سے چھوٹی تھی) اور وہ پتے اور پھول اور بیج گھر لے گئی۔ مورتی تو خیر کسی نے سونے چاندی،ہیرے اور پنوں کی وجہ سے چرائی لیکن گاندھرو داس کو لارسن اینڈ لارسن کے مالک ڈروے نے بے وجہ خرید لیا۔گاندھرو داس اور ڈروے میں کوئی بات نہیں ہوئی۔بوڑھے نے صرف آنکھوں ہی آنکھوں میں اسے کہہ دیا جیسے تیسے بھی ہو،مجھے لے لو بیٹے۔بنا بیٹے کے کوئی باپ نہیں ہو سکتا اس کے بعد ڈروے کو آنکھیں ملانے سوال کرنے کی ہمت ہی نہ پڑی۔سوال شرطوں کا تھا مگر شرطوں کے ساتھ کبھی زندگی جی جاتی ہے؟ڈروے نے گاندھرو داس کا قرض چکایا۔سہارا دیکر اسے اٹھایا اور مالا بارہل کے دامن میں اپنے عالیشان بنگلے گری گنج لے گیا جہاں وہ اس کی تیمار داری اور خدمت کرنے لگا۔ ڈروے سے اس کے ملازموں نے پوچھا۔سر آپ یہ کیا مصیبت لے آئے ہیں۔یہ بڈھا،مطلب،بابو جی آپ کو کیا دیتے ہیں۔ کچھ نہیں بیٹھے رہتے ہیں آلتی پالتی مارے کھانستے رہتے ہیں اور یا پھر زردرے والے پان چباتے جاتے ہیں۔جہاں جی چا ہے تھوک دیتے ہیں۔جس کی عادت مجھے اور میری صفائی پسند بیوی کو بھی نہیں پڑی۔مگر پڑ جائے گی۔دھیرے دھیرے....مگر تم نے ان کی آنکھیں دیکھی ہیں؟ جی نہیں۔ جاؤ دیکھو ان کی روتی ہنستی آنکھوں میں کیا ہے ان میں کیسے کیسے سندیس نکل کر کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟ کہاں کہاں پہنچ رہے ہیں؟.... جمنا داس ڈورے کے ملازم نے غیر ارادی طور پر فضا میں دیکھتے ہوئے کہا.... آپ سائنسداں ہیں ! میں سائنس کی بات کر رہا ہوں۔ جمنا !اگر انسان کے زندہ رہنے کے لئے پھل پھول پیڑ پودے ضروری ہیں، جنگل کے جانور ضروری ہیں تو بو ڑھے بھی ضروری ہیں۔ورنہ ہمارا ایکولا جیکل بیلنس تباہ ہو جائے گا اگر جسمانی طور پر نہیں تو روحانی طور پر بے وزن ہو کر انسانی نسل ہمیشہ کے لئے معدوم ہو جائے۔ جمانا داس اور اتھا��لے بھاؤ کچھ سمجھ نہ سکے۔ ڈروے نے بنگلے میں لگے شوک پیڑ کا ایک پتا توڑا اور جمنا داس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا اپنی پری سائنس سے کہو کہ یہ تازگی یہ شگفتگی، یہ شادابی اور یہ رنگ پیدا کر کے دکھائے.... اتھادلے بولا وہ تو اشوک کا بیج بوئیں .... آں ہاں ....ڈروے نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔میں بیج نہیں پتے کی بات کر رہا ہوں۔بیج کی بات کریں گے تو ہم خدا جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ پھر جمنا داس کے قریب ہوتے ہوئے ڈروے بولا میں تمہیں کیا بتاؤں جمنا جب میں بابو جی کے قدم چھو کر جاتا ہوں تو ان کی نگاہوں کا عزم مجھے کتنی شانتی کتنی ٹھنڈک دیتا ہے میں جوہر وقت ایک بے نام ڈر سے کانپتا رہتا تھا اب نہیں کانپتا ....مجھے ہر وقت اس بات کی تسلی رہتی ہے وہ تو ہیں۔مجھے یقین ہے بابو جی کو بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہو گا،میں نہیں مانتا سر....یہ خالی خولی جذباتیت ہے۔ ہو سکتا تھا۔ ڈروے بھڑک اٹھتا ہو سکتا تھا وہ جمنا داس، اپنے ملازم کو اپنی فرم سے ڈسمس کر دیتا لیکن باپ کی آنکھوں کے دم نے اسے یہ نہ کرنے دیا۔اس کی آواز میں الٹا کہیں سے کوئی سر چلا آیا اور اس نے بڑے پیا ر سے کہا،تم کچھ بھی کہہ لو،جمنا ہر ایک بات تو تم جانتے ہو میں جہاں جاتا ہوں لوگ مجھے سلام کرتے ہیں۔میرے سامنے سر جھکا تے ہیں۔بچھ بچھ جاتے ہیں۔ ڈروے اس کے بعد ایکا ایکی چپ ہو گیا اس کا گلا اور آنکھیں دھندلا گئیں۔سر میں بھی تو یہی کہتا ہوں ....دنیا آپ کے سامنے سر جھکاتی ہے!اس لیے....ڈروے نے اپنی آواز پاتے ہوئے کہا ....کہیں میں بھی سر جھکانا چاہتا ہوں۔اتھاولے،جمناداس اب تم جاؤ پلیز !میری پوجا میں دکھن مت ڈالو،ہم نے پتھر سے خدا پایا ہے۔ گری گنج میں لگے ہوئے آ م کے پیڑوں میں بور پڑا۔ ادھر پہلی کوئل کوکی ادھر گاندھرو داس نے برسو ں کے بعد تان اڑائی.... کوئلیا بولے اموا کی ڈال ....وہ گانے لگے کسی نے کہا۔آپ کا بیٹا آپ سے اچھا گاتا ہے۔ امٹیا....گاندھرواس نے،عیبا بولی میں کہا ....آخر میرا بیٹا ہے۔باپ نے میٹرک کیا ہے تو بیٹا ایم اے نہ کرے؟ ایسی باتیں کرتے ہوئے ناسمجھ بے باپ کے لوگ گاندھرو داس کی طرف د��کھتے کہ ان کی جھریو ں میں کہیں تو جلن دکھا ئی دے جب کوئی ایسی چیز نظر نہ آئی تو کسی نے لقمہ دیا آپ کا بیٹا کہتا ہے،میرا باپ مجھ سے جلتا ہے۔ سچ؟....میرا بیٹا کہتا ہے۔ ہاں،میں جھوٹ تھوڑے بول رہا ہوں۔ گاندھرو داس تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے جیسے وہ کہیں اندر عالم ارواح میں چلے گئے ہوں اور ماں سے بیٹے کی شکایت کی ہو۔بڑھیا سے کوئی جواب پا کر وہ دھیر ے سے بولے ....اور تو کوئی بات نہیں، میرا بیٹا.... وہ بھی باپ ہے ....وہ پھر ان دنوں کی طرف لوٹ گئے جب بیٹے نے کہا تھا۔بابو جی میں شاستریہ سنگیت میں آپ ایسا کمال پیدا کرنا چاہتا ہو ں مگر ڈھیر سارا روپیہ کما کر۔اور بابو جی نے بڑی شفقت سے بیٹے کے کندھے تھپ تھپاتے ہوئے کہا ....ایسے نہیں ہوتا راجو ....یا آدمی کمال حاصل کرتا ہے یا پیسے ہی بناتا چلے جاتا ہے جب دو بڑے بڑے آنسو لڑھک کر گاندھرو داس کی داڑھی میں اٹک گئے جہاں ڈروے بیٹھا تھا۔ ادھر سے روشنی میں وہ ضم ہو گئے سفید روشنی جن میں سے نکل کر سات رنگوں میں بکھر گئی۔ ڈروے کو نہ جانے کیا ہوا وہ اٹھ کر زور سے چلا یا.... گیٹ آؤٹ ....اور لوگ چوہوں کی طرح ایک دوسرے پر گرتے پڑتے ہوئے بھاگے۔ گاندھرو داس نے اپنا ہاتھ اٹھا یا اور صرف اتنا کہا .... نہیں بیٹے نہیں۔ ان کے ہاتھ سے کوئی برقی روئیں نکل رہی تھیں۔ ڈروے جب لارسن اینڈ لارسن میں گیا تو فلپ، اس کا ورکس مینجر کمپیوٹر کو ڈیٹا فیڈ کر رہا تھا کمپیوٹر سے کارڈ باہر آ یا تو اس کا رنگ پیلا پڑ گیا وہ بار بار آنکھیں جھپک رہا تھا اور کارڈ کی طرف دیکھ رہا تھا لارسن اینڈ لارسن کو اکتا لیس لاکھ کا گھاٹا پڑنے والا ہے اس گھبراہٹ میں اس نے کارڈ ڈروے کے سامنے کر دیا جسے دیکھ کر اس کے چہرے پر شکن تک نہ آئی۔ ڈروے نے صرف اتنا کہا۔ کوئی انفارمیشن غلط فیڈ ہو گئی ہے۔ نہیں سر ....میں نے بیسوں بار چیک کراس چیک کر کے اسے فیڈ کیا ہے۔ تو پھر مشین ہے کوئی نقص پیدا ہو گیا ہو گا۔ آئی بی ایم والوں کو بلاؤ۔ مودک چیف انجینئر تو ساؤتھ گیا ہے۔ ساؤتھ کہاں؟ ترپتی کے مندر سنا ہے اس نے اپنے لمبے ہپی بال کٹوا کر مورتی کی نذر کر دیئے ہیں۔ ڈروے ہلکا سا مسکرایا اور بولا تم نے یہ انفارمیشن فیڈ کی ہے کہ ہمارے بیچ ایک باپ آیا ہے؟ فلپ نے سمجھا ڈروے اس کا مذاق اڑا رہے ہیں یا ویسے ہی ان کا دماغ پھر گیا ہے مگر ڈروے کہتا رہا.... اب ہمارے سر پر کسی کا ہاتھ ہے تبریک ہے اس کے نتیجے کا حوصلہ اور ہمت مت بھولو۔ یہ مشین کسی انسان نے بنائی ہے جس کا کوئی باپ تھا۔ پھر اس کا باپ اور آخر سب کا باپ جہل مرکب یا مفرد ! فلپ نے اپنی اندرونی خفگی کا منہ موڑ دیا۔کیا دیویانی اب بھی بابو جی کے پاس آتی ہے۔ ہاں۔ مسز ڈورے کچھ نہیں کہتی۔ پہلے کہتی تھیں۔ اب وہ ان کی پوجا کرتی ہیں۔ بابو جی دراصل عورت کی جات ہی سے پیار کرتے ہیں۔ فلپ معلوم ہوتا ہے۔ انہوں نے کہیں پر کرتی کے چتون دیکھ لئے ہیں۔ جن کے جواب میں وہ مسکراتے تو ہیں لیکن کبھی کبھی بیچ میں آنکھ بھی مار دیتے ہیں۔ فلپ کاغصہ اور بڑھ گیا۔ ڈروے کہتا....بابو جی کو شبد، بیٹی، بہو، بھابی، چاچی، للی، میا، بہت اچھے لگتے ہیں۔ وہ بہو کی کمر میں ہاتھ ڈال کر پیار سے اس کا گال چوم لیتے ہیں اور یوں قید میں آزادی پا لیتے ہیں۔ اور آزادی میں قید دیویانی؟ ڈروے نے حقارت سے کہا۔ سیکس کو اتنی ہی اہمیت دو جتنی کا وہ مستحق ہے۔ تیتر بٹیر بنے بغیر اس کے حواس پر مت چھانے دو۔ سنگیت شاید ایک آرتی دیویانی کے لئے میں سمجھا نہیں سر؟ بابو جی نے بتایا کہ وہ لڑکی بچپن ہی میں آوارہ ہو گئی۔ اس نے اپنے باپ کو کچھ اس عالم میں دیکھ لیا جب کہ و ہ نو خیزی سے جوانی میں قدم رکھ رہی تھی۔ جب سے وہ ہمیشہ کے لئے آ پ ہی اپنی ماں ہو گئی۔ باپ کے مرنے کے بعد وہ گھبرا کر ایک مرد سے دوسرے،دوسرے سے تیسرے کے پاس جانے لگی۔ اس کا بدن ٹوٹ ٹوٹ جاتا تھا۔ مگر روح تھی کہ تھکتی ہی نہ تھی۔ کیا مطلب؟ دیویانی کو دراصل باپ ہی کی تلاش تھی۔ فلپ جو ایک کیتھولک تھا ایک دم بھڑک اُٹھا، اس کے ابرو بالشت بھر اُوپر اُٹھ گئے اور پھیلی ہوئی آنکھو ں سے نار جہنم لپکنے لگی۔ اس نے چلا کر کہا....یہ فراڈ ہے۔ مسٹر ڈروے پیور۔ این او لٹر ہیڈ فراڈ جبھی ڈروے نے اپنے خریدے ہوئے باپ کی نم آنکھوں کو درنے میں لئے، کمپیوٹر کے پس منظر میں کھڑے فلپ کی طرف دیکھا اور کہا.... آج ہی بابو جی نے کہا تھا، فلپ تم انسان کو سمجھنے کی کوشش نہ کرو صرف محسوس کرو اسے ....! ٭٭٭ Read the full article
0 notes
Photo

کبھی شہرت کو سنجیدہ نہیں لیا، ’’بہاؤ‘‘ جیسا ناول اب خود بھی نہیں لکھ سکتا دریا کبھی یکساں نہیں رہتا۔۔۔وہ بدلتا رہتا ہے۔ کبھی خاموش، کبھی غصیل، کبھی مٹیالا، کبھی شفاف۔ مسلسل بہتے ہوئے وہ موسمی اثرات قبول کرتا ہے، جغرافیائی تبدیلیوں سے ہم آہنگ ہوتا ہے۔ بدلتا جاتا ہے۔ اور یوں ہر بار دریا اپنے ملاقاتی کو ایک نئی کہانی سناتا ہے۔ ایک ان کہی کہانی۔ ہزاروں قارئین کی زندگی پر دیر پا اثرات مرتب کرنے والے عہدساز ادیب، مستنصر حسین تارڑ بھی ایک ایسے ہی دریا کے مانند ہیں، جن سے ہر ملاقات میں، ہر مکالمے میں ایک نئی کہانی سامنے آتی ہے۔ گذشتہ دنوں ’ادب فیسٹول پاکستان‘ میں شرکت کے لیے وہ کراچی آئے، تو اُن کے ساتھ ایک طویل نشست ہوئی، جس میں اردو کی تاریخ کے اِس مقبول ترین لکھاری نے اردو زبان، اپنے ہم عصروں، اردو ادب کے مستقبل پر، اپنے مخصوص بے ساختہ انداز میں تفصیلی اظہار خیال ہے۔ اس روز موسم خوش گوار تھا۔ آسمان پر بادل تھے۔ ہم کراچی جم خانے پہنچے، تو وہ منتظر تھے۔ نشست سنبھالنے کے بعد پوچھا کیے، آپ نے اپنے کیریئر میں ناول لکھے، سفر نامے ، ڈرامے لکھے، ڈراموں میں کام کیا، وہ کون سا کام تھا، جس میں خود کو تخلیقی طور پر زیادہ مطمئن اور مسرور محسوس کیا؟ تو کہنے لگے کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں، پوری سنجیدگی سے کرتا ہوں، اور اُس میں مکمل طور پر شامل ہوجاتا ہوں۔ ’’ چاہے کمپیئرنگ ہو، ایکٹنگ ہو، سفرنامہ ہو، ناول ہو، I am totally committed to it۔ اور اُس وقت وہ میرے لیے سب سے اہم ہوتا ہے، میں تخصیص نہیں کرتا کہ یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے، وہ کم اہم۔ البتہ جب آپ ایک ناول لکھتے ہیں، تو اس کی باگیں آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہیں، سفرنامہ لکھتے ہوئے آپ کو کراچی سے لاہور جانا ہے، تو راستہ میں گلگت نہیں آئے گا، وہ راستہ طے شدہ ہے۔ البتہ ناول طے شدہ نہیں ہوتا۔ کم از کم میرے ناول طے شدہ نہیں ہوتے۔ ناول میں چیزوں کو manipulate کرنے کا اختیار ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تخلیق کار خود کو چھوٹا سا خدا سمجھتے ہیں، کیوں کہ تخلیق کر رہے ہوتے ہیں۔ جس طرح کئی لوگ خدا سے باغی ہوجاتے ہیں، اِسی طرح کچھ کردار ناول نگار سے باغی ہوجاتے ہیں۔ وہ اپنا راستہ خود بناتے ہیں، اور وہاں سے ناول بڑا بنتا ہے، کیوں کہ اگر تمام کردار آپ کی مرض�� کے مطابق چل رہے ہیں، تو آپ کی زبان بول رہے ہیں، آپ کی فکر کی تقلید کر رہے ہیں، لیکن اگر باغی ہوجاتے ہیں، تو اُن کی اپنی فکر سامنے آتی ہے۔ تو ناول لکھتے ہوئے تخلیقی عمل کی جو طمانیت ہوتی ہے، وہ الگ ہے۔ تاج محل جنھوں نے بنایا ہوگا، انھوں نے کہا ہوگا کہ خدا، تو نے ہمیں بنایا، اور دیکھ ہم نے تاج محل بنایا۔ تو ناول میں یہ معاملہ ہے۔‘‘ زندگی کے ایک خاص موڑ پر تارڑ صاحب نے شوبز کی دنیا ترک کی، اور خود کو کلی طور پر لکھنے کے لیے وقف کردیا۔ اِسی تناظر میں ہم نے پوچھا، شہرت تو بڑی سحرانگیز ہوتی ہے، کیا یہ مشکل فیصلہ نہیں تھا؟ کہنے لگے،’’کسی زمانے میں لگاتار دو برس میں گیلپ کے سروے میں پاکستان کا مقبول ترین شخص ٹھہرا۔ اب یہ شہرت کی انتہا ہوسکتی ہے۔ تب میں کسی محفل میں گیا، وہاں اور بھی لکھنے والے تھے، مگر بہت سے لوگ میری طرف آئے۔ جب میں فری ہوا، تو دیکھا، ممتاز مفتی مجھے گھور رہے ہیں۔ وہ میرے پاس آئے اور کہا کہ تم میں بڑا رائٹر بننے کی تمام تر صلاحیتیں ہیں، مگر تم نہیں بن سکو گے۔ یہ شہرت تمھیں کھا جائے گی۔ میں نے انھیں کہا کہ مفتی صاحب، میں حلفیہ کہتا ہوں، میں نے کبھی اِسے سنجیدگی سے نہیں لیا، یہ ایک عارضی معاملہ ہے۔ میڈیا میری مجبوری ہے، کیوں کہ مجھے گھر کا خرچ چلانا ہے۔ کہنے لگے، نہیں اگر میڈیا نہیں چھوڑو گے، تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ خیر، چند برس بعد انھوں نے مجھے خط لکھا، جس کے مندرجات میں پورے بیان نہیں کرسکتا، مگر انھوں نے مجھ سے معذرت کی، اور لکھا کہ تم نے مجھے غلط ثابت کیا، شہرت تم پر اثرانداز نہیں ہوسکی۔ آگے انھوں نے ایک حوالہ دیا کہ فلاں پر شہرت نے اثر کیا، اور اس میں جو ٹیلنٹ تھا، وہ اس کا اظہار نہیں کرسکا۔‘‘ گو تارڑ صاحب نے تذکرہ تو نہیں کیا، مگر ہمارے ذہن میں پہلا خیال اشفاق احمد کا آیا، اسی تناظر میں پوچھا، کیا اشفاق احمد نے ناولز نہ لکھ کر اپنے فن کے ساتھ ناانصافی کی؟ ان کا کہنا تھا کہ اشفاق صاحب اپنے عہد کے نمایندہ شخصیت تھے۔ بنیادی طور پر وہ داستان گو تھے۔ اُن جیسی گفتگو بہت کم لوگ کرسکتے ہیں۔ ’’میں نے ان کے کئی ڈراموں میں کام کیا، روحی بانو کے ساتھ میں نے جو ڈرامے کیے، زیادہ تر اُن ہی کے لکھے ہوئے تھے۔ میں انھیں ٹیلی ویژن کی تاریخ کا سب سے بڑا ڈراما نگار مانتا ہوں، انھوں نے جن موضوعات کو اٹھایا، لوگ آج بھی اٹھانے سے گھبراتے ہیں، یہ تو ہوئی ڈرامے کی بات۔ اگر لٹریچر کی بات کی جائے، تو وہاں لوگ ٹھوس ثبوت مانگتے ہیں، اور ثبوت انھوں نے کم چھوڑے۔ ریڈیو میں بہت دل چسپی تھی، تلقین شاہ ایک کلاسیک تھا، پھر ’زاویہ‘ تھا، مگر میری یہ خواہش تھی کہ وہ ناولز لکھتے کہ ان میں تمام تر صلاحیت موجود تھی، جب کہ بانو آپا نے ’راجہ گدھ‘ لکھ دیا۔ البتہ یہ ان کی صوابدید اور اختیار تھا۔ اگر انھوں نے مناسب سمجھا کہ ریڈیو اور ٹی وی کو زیادہ وقت دیں، اپنی بابا شخصیت کو زیادہ پراجیکٹ کریں، تو یہ ان کا اپنا انتخاب تھا۔‘‘ کیا ناول نگاری اور سفرنامہ نویسی کا فن یک سر الگ ہے؟ تارڑ صاحب اِس کا جواب اثبات میں دیتے ہیں۔ اُن کے بہ قول،’’بالکل، سفرنامہ طے شدہ ہے۔ آپ تھوڑا اِدھر ادھر نکل جائیں گے، بس۔ جیسے ’سنو لیک‘ میں مَیں قرۃ العین طاہرہ کو یاد کرتا ہوں، وہ الگ معاملہ ہے، مگر ناول طے شدہ نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں، ہر گام پر ہمیں ایک کہانی نظر آتی ہے، مجھے نہیں آتی۔ کچھ ادیب کہتے ہیں کہ پورا تصور ذہن میں آگیا، میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی سچویشن ہوتی ہے، فقرہ آتا ہے، احساس ہوتا ہے، جو مجھے تحریک دیتا ہے۔‘‘ تارڑ صاحب نے کہیں لکھا تھا کہ عبداللہ حسین واحد ادیب ہیں، جن سے اُن کی دوستی تھی۔ اُن کی بابت پوچھا، تو فرمایا،’’ہم دونوں ایک دوسرے کے رازداں تھے۔ وہ ایک ایب نارمل انسان تھے، اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کوئی نارمل ادیب بڑا ادیب نہیں بن سکتا، کیوں کہ قاری آپ سے ایب نارمل اور معمول سے ہٹ کر لٹریچر اور کرداروں کی توقع کرتا ہے، اور یہ تب ہی ممکن ہے، جب آپ ایک بے راہ رو قسم کی زندگی گزاریں۔ اور وہ تمام تجربات آپ کے پاس ہوں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں، ناول کے لیے ایک ولی اللہ سے لے کر ایک طوائف تک، تمام طبقات کے تجربات آپ کے پاس ہونے چاہییں، تب ہی آپ ناول لکھ سکتے ہیں۔ عبداللہ حسین کے پاس وہ تمام تجربات تھے۔ کم لکھا، کیوں کہ عرصہ دراز وہ باہر رہے، مگر جتنا بھی لکھا، وہ بالکل مختلف لکھا۔‘‘ وہ کراچی میں ایک فیسٹول میں شرکت کے لیے آئے تھے، اِسی تناظر میں پوچھا، آج میگاایونٹس ہورہے ہیں، ادبی کانفرنسیں، میلے ، فیسٹولز، کیا یہ سرگرمیاں فروغ ادب میں معاون ہیں، یا پھر وہ ادبی نشستیں ، جو ماضی میں ہوا کرتی تھیں، زیادہ اثر انگیز تھیں؟ بلاتامل کہا،’’وہ نشستیں زیادہ اثرانگیز تھیں۔ یہ کمرشل سرگرمی ہے، اسپانسر آتے ہیں۔ ہم جیسوں کو فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دیگر ادیبوں سے ملاقات ہوجاتی ہے۔ لوگ مل بیٹھتے ہیں۔ میرے نزدیک پیمانہ یہ ہے کہ فیسٹول میں ادیبوں کی کتابیں کتنی فروخت ہوئیں؟ اگر نہیں ہوئیں، تو وہ فیسٹول بے معنی ہے۔ میرے نزدیک اہم یہ ہے کہ لوگ کتابیں خریدیں۔ پھر یہ کہ نئے ٹیلنٹ کی آب یاری ہو۔ وہ نہیں ہورہی۔ یہاں اسٹارز زیادہ بلائے جاتے ہیں، بدقسمتی سے میں بھی ان اسٹارز میں شامل ہوں۔ میں دو تین درجن ایسے اہم ادیبوں کا حوالہ دے سکتا ہوں، جنھیں میں نے کبھی کسی فیسٹول میں نہیں دیکھا۔ یہ بہت ناانصافی ہے۔‘‘ ہم نے کہا، آپ نے اکثر اپنے کالموں میں الطاف فاطمہ کا ذکر کیا، وہ بھی نوّے برس کی عمر میں گذشتہ سال ہم سے جدا ہوگئیں۔ کہنے لگے، الطاف فاطمہ صوفی اور درویش قسم کی خاتون تھیں۔ ’’مجھے معلوم ہے کہ کئی بار اکیڈمی آف لیٹرز نے انھیں اپروچ کیا کہ ہم پرائیڈ آف پرفارمینس کے لیے آپ کا نام دے دیتے ہیں، مگر انھوں نے منع کر دیا۔ حالاں کہ انھیں مالی مسائل درپیش تھے، مگر انھوں نے مالی معاونت گوارا نہیں کی۔ یہ کہہ دیا کہ آپ مجھے ترجمے کا کام دے دیں۔ الگ تھلگ رہتی تھیں۔ میرا اُن سے خاص تعلق تھا، کوئی پچاس برس پہلے سے۔ ان کی پرانی کوٹھی تھی، میں وہاں جایا کرتا، ان سے باتیں کیا کرتا۔ میرے لیے ایک fascination یہ بھی تھی کہ ان کے ماموں سید رفیق حسین تھے، اور میرے نزدیک دنیا بھر میں کسی نے جانوروں کے بارے میں اتنا اچھا ادب نہیں لکھا، جتنا سید رفیق حسین نے لکھا ہے۔ وہ دراصل انسان نہیں تھے، ایک بارہ سنگھا تھے، ایک شیر تھے۔ وہ ان جانوروں کے قالب میں ڈھل جاتے تھے۔ تو الطاف فاطمہ کی زبان میں بناوٹ نہیں تھی، وہ ایسی رواں اور سریلی تھی کہ دل میں اترتی چلی جاتی۔ ان کے کسی افسانے میں ایک جملہ پڑھا، تو میں نے سوچا کہ یہ صورت حال، جو الطاف نے ایک جملے میں لکھی، اگر مجھے لکھنی ہوتی، تو شاید پورا صفحہ لکھتا۔ میرے سفرناموں کو وہ بہت سراہتی تھیں، خاص کر ’اندلس میں اجنبی‘ کے کوٹس مجھے بھیجا کرتی تھیں۔ ان کے جانے کا بہت دکھ ہوا۔ اِس وجہ سے بھی وہ ادیبوں کی جو Rat race ہے، کبھی اس کا ��صہ نہیں بنیں، مین اسٹریم میں آئی ہی نہیں۔ اور انھیں اُس کا کوئی غم بھی نہیں تھا۔‘‘ کیا لکھنے والا تخلیقی عمل کے دوران اُس شہرت اور محبت کا دباؤ محسوس کرتا ہے، جو اُس کے حصے میں آئی، کیا تارڑ صاحب کبھی ایسے کسی تجربے سے گزرے؟ اس کا جواب وہ نفی میں دیتے ہیں۔ اُن کے بہ قول، لکھتے وقت میں ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہوں۔ مجھے یہ فکر نہیں ہوتی کہ جو کچھ میں لکھ رہا ہوں، اسے بقائے دوام حاصل ہوگی، پسندیدگی حاصل ہوگی، یا یہ بڑا ادب بنے گا۔ اس وقت میں اُس میں اتنا شامل ہوتا ہوں کہ میں فقط اپنے لیے لکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو کوئی پریشر نہیں ہوتا۔ ہاں، ایک بات کا دھیان رکھتا ہوں، میں قاری کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ یہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ مجھے بات کو سہل کرنا ہے۔ بہت سے دوست کہتے ہیں کہ قاری خود کو ایجوکیٹ کرے، ہماری سطح پر آئے، مگر میں ایسا نہیں کرتا، میں خود کو تھوڑا نیچا کرکے قاری کی سطح پر چلا جاتا ہوں۔‘‘ اگر وہ ابلاغ کو اہمیت دینے والے ادیبوں کے قبیلے سے ہیں، تو اُس پُرپیچ ادب کو کیسے دیکھتے ہیں، جو انور سجاد کے قبیلے کے ادیبوں نے لکھا؟ کہنے لگے،’’انور سجاد ماڈرن اسٹوری کے بانیوں میں سے ہیں۔ انور کی نثر میں ایک خاص ردھم ہے، اس میں ایک پیٹرن ہے۔ انور نے، بلراج من را نے جو کچھ لکھا، اس کا اثر ہے، اس سے بچا نہیں جاسکتا۔ اُسے ہم نظرانداز نہیں کرسکتے۔ وہ اہم تھا۔ تجربات ہوتے رہتے ہیں، نئے لکھنے والے ان سے سیکھتے ہیں، اور اپنی راہ خود نکالتے ہیں۔‘‘ عام رائے ہے کہ اردو ادب یوں عالمی دنیا تک نہیں پہنچا کہ یہ کم زور ہے، مگر اِسی خطے کی کہانیاں بیان کرنے والے یہاں کے انگریزی ادیب بین الاقوامی اعزازات حاصل کر رہے ہیں۔ یہ مسئلہ بہ طور سوال ان کے سامنے رکھا، تو کہنے لگے،’’ترجمے کا شعبہ اردو میں بہت کم زور ہے، بالکل نہ ہونے کے برابر ہے۔ ترکی، عربی زبانوں میں دنیا بھر کا عالمی ادب موجود ہے۔ چینی حکومت کی دعوت پر میں سنکیانگ گیا۔ وہاں ایغور زبان بولی جاتی ہے، جس کا ہم نے نام بھی نہیں سنا ہوگا۔ آپ تو یہی کہتے ہیں کہ اردو کی بڑی دھوم ہے، ٹھیک ہے، دھوم ہوگی، ایغور کی تو دھوم نہیں، مگر اس میں بھی تمام روسی ادب، کلاسیکی ادب موجود ہے۔ اور ہمارے ہاں ایسا نہیں۔ شاید یہ سبب ہو کہ انگریزی ہماری سیکنڈ لینگویج ہے، جسے خواہش ہوتی ہے، وہ انگریزی میں پڑھ لیتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ اردو ادب کم زور ہے، اس کا ترجمہ ہوا ہی نہیں، وہ پہنچا ہی نہیں۔ میں نے جو ایرانی، ترکی اور دیگر زبانوں کے ناولز پڑھے ہیں، ہمارے ناول ان سے کم تر نہیں، مگر ان کا ترجمہ نہیں ہوا۔ اب آتے ہیں کہ انگریزی میں لکھنے والوں پر۔ یہ اچھی بات ہے کہ لوگ انگریزی میں لکھ رہے ہیں، میری انگریزی اچھی ہوتی، تو شاید میں بھی لکھتا، مگر جب بین الاقوامی سطح پر کوئی فہرست ترتیب پاتی ہے، تو اِس خطے کے انگریزی میں لکھنے والے اُس میں جگہ نہیں بنا پاتے۔ ہاں، یہاں ان کی اہمیت ہے۔ اور بہت سے اچھے لکھنے والے ہیں۔ محمدحنیف، ندیم اسلم ہیں، ایم ایچ نقوی اور کاملہ شمسی ہیں، مگر ان میں سے بیش تر وہی موضوع اور کردار دہرا رہے ہیں، جو ہم کب کے لکھ چکے۔ دراصل تراجم کے لیے پورے ادارے چاہییں۔ اب جنوبی کوریا کو نوبیل انعام نہیں ملا، تو اُنھوں نے مہم شروع کر رکھی ہے۔ یہاں ایسا معاملہ نہیں ہے، حکومتوں کی سطح پر ادب کو سنجیدہ نہیں لیا جاتا۔‘‘ راقم الحروف نے جو ناولز پڑھے، اُن میں جنھوں نے سب سے زیادہ متاثر کیا، مستنصر حسین تارڑ کا ’بہاؤ‘ ان میں سے ایک ہے۔ تین عشروں قبل شایع ہونے والے اس ناول کا شمار اب کلاسیک میں ہوتا ہے، ادبی جریدے ’ذہن جدید‘ کے سروے میں اس کا ذکر اردو کے دس بہترین ناولز میں کیا گیا، بی بی سی نے اس کا موازنہ مارکیز کے ’تنہائی کے سو سال‘ سے کیا۔ تو ہم نے پوچھا، آج جب پلٹ کر دیکھتے ہیں، تو اپنی تخلیقات میں اِسے کہاں کھڑا پاتے ہیں؟ کہنے لگے کہ ’بہاؤ‘ جیسا ناول اب وہ خو د بھی نہیں لکھ سکتے۔ ’’پانچ ہزار سال پہلے جانا، ایک خاص کیفیت میں کلام کرنا، وہ میں دوبارہ نہیں کرسکتا۔‘‘ اُنھیں اپنے ناولز کا اردو کے کلاسیک ناولز سے موازنہ پسند نہیں۔ بہ قول اُن کے،’’جب بھی میرا کوئی ناول چھپتا ہے، اور اگر اچھا ہوتا ہے، تو کراچی میں اس کا موازنہ کیا جاتا ہے کہ ’آگ کا دریا‘ سے اچھا ہے یا نہیں۔ ہندوستانی ادیب ، مشرف عالم ذوقی نے میرے ناول ’خس و خاشاک زمانے‘ کو ’آگ کا دریا‘ سے آگے کی چیز قرار دیا تھا۔ مگر میں سمجھتا ہوں کہ ہر ادیب اپنی جگہ اہم ہوتا ہے، موازنہ ممکن نہیں۔ ہم اورحان پامک کا موازنہ یاشر کمال سے نہیں کرسکتے۔ مگر ہمارے ہاں موازنہ ہوتا ہے۔ قرۃ العین لاہور آئیں، تو چند نقاد بیٹھے۔ انھوں نے ابتدائی تمام سوالات ’آگ کا دریا‘ کے بارے میں کیے، وہ واک آؤٹ کر گئیں کہ میں نے اُس کے بعد بھی چار پانچ ناولز لکھے ہیں، آپ نے وہ نہیں پڑھے؟ جب مجھ سے باربار پوچھا گیا کہ کیا آپ ’آگ کا دریا‘ جیسا ناول لکھ سکتے ہیں، تو میں نے تنگ آکر کہا کہ نہیں، وہ تو عینی آپا کا ہے، مگر قرۃ العین حیدر بھی ’بہاؤ‘ نہیں لکھ سکتیں۔‘‘ ہم نے کہا، لگتا ہے، ناول کی بحث ’آگ کا دریا‘، ’اداس نسلیں‘ اور ’خدا کی بستی‘ پر آن کر ختم ہوجاتی ہے، تو انھوں نے ہم سے اتفاق کیا۔ کہنے لگے،’’دراصل آپ کو علم نہیں ہے۔ پتا ہی نہیں کہ کیا کیا لکھا جارہا ہے۔ آپ اسی پر تکیہ کرتے ہیں، جو آپ نے لکھا، دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوتا۔‘‘ تارڑ صاحب کی شہرت کے کئی اسباب، مگر جس ہنر نے ہمیں گرویدہ بنایا، وہ ناول نگاری ہے۔ اُن کا آخری ناول ’اے غزال شب‘ تھا، جس کے بعد خاموشی چھا گئی، چند برس پہلے کراچی میں ملے، تو انھوں نے یہی کہا تھا کہ فی الحال کوئی ناول ذہن میں نہیں، مگر رواں برس کے آخر میں ’منطق الطیر، جدید‘ آیا، جو فرید الدین عطار کے کلاسیک کا ماڈرن روپ ہے۔ اِس بار ملے، تو ہم نے پوچھا، یہ وقفے کیسے ختم ہوا؟ ان کا کہنا تھا،’’اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ناول لکھتے ہوئے ہی آپ کے ذہن میں کوئی نیا خیال، کوئی ایسی چیز آجاتی ہے، جس پر آپ مستقبل میں قلم اٹھائیں۔ ’اے غزال شب‘ کے بعد میرے پاس ایسا کوئی خیال نہیں تھا، نہ ہی میں لکھنا چاہتا تھا۔ مگر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عطار میرے مرشد ہیں، میں پچاس سال سے اُن کے پرندوں کے عشق میں مبتلا ہوں، تو ان کا ایک تازہ ترجمہ انگریزی میں ہوا، اور انگریزی میں ترجمے ہوتے رہے ہیں۔ جیسے رومی کا پہلے بھی ترجمہ ہوا تھا، مگر بعد میں جو ترجمہ ہوا، اس کی وجہ سے اُنھیں دنیا کا سب سے بڑا صوفی قرار دیا گیا۔ تو ’منطق الطیر‘ کے پہلے بھی تراجم ہوئے، مگر جو تازہ ہوا، وہ میں نے پڑھا، تو میرے ذہن میں آیا کہ جیسے پرانی داستانوں کو بار بار لکھا جاتا ہے، ہیر رانجھا اور مرزا صاحباں کو بار بار لکھا گیا، تو یہ بھی ایک کلاسیک ہے، اس کی بھی پیروی کرنی چاہیے۔ گو فریدالدین عطار کے نقش قدم پر چلنا، اپنے پیروں کو جلانے کے مترادف ہے، مگر ’بہاؤ‘ کے بعد جس ناول کو لکھتے ہوئے میں نے چیلینج محسوس کیا، وہ جس طرح کہتے ہیں، کچھ چیزیں اترتی بھی ہیں، وہ ’منطق الطیر جدید‘ ہی ہے۔‘‘ ہم نے کہا،’آگ کا دریا‘، ’اداس نسلیں‘،’کئی چاند تھے سر آسماں‘، ان کے مصنفین نے خود ہی اپنے ناولز کا ترجمہ کیا، کبھی ایسا خیال آپ کے ذہن میں آیا؟ تو کہا،’’مسئلہ یہ ہے کہ اگر میں ’راکھ‘ کا ترجمہ کروں، تو دو سال لگ جائیں گے، تو دو سال میں ترجمہ کیوں کروں؟ نیا ناول کیوں نہ لکھوں؟ اگر ’راکھ‘ اور ’بہاؤ‘ میں قوت ہے، تو لوگ بعد میں خود ہی اُن کا ترجمہ کر لیں گے۔ میرے پاس جو محدود ٹائم ہے، میں چاہوں گا کہ جو بھی مجھ پر اتر رہا ہے، اُسے قلم بند کروں، دوسری بات یہ ہے کہ جب آدمی خود ترجمہ کرتے ہیں، تب یا تو اُسے ایڈٹ کرتا جاتا ہے، یا پھر اُسے تبدیل کرتا جاتا ہے، جس سے اُس کی ہیئت تبدیل ہو جاتی ہے۔ عبداللہ حسین نے ترجمہ کیا، قرۃ العین نے کیا۔ آج آپ اُنھیں پڑھ ہی نہیں سکتے، ان میں Readability ہے ہی نہیں۔ اس کے برعکس میرے ناول ’اے غزال شب‘ کا ’لینن فار سیل‘ کے نام سے ترجمہ ہوا، اس کی سیل بھی ہوئی، اور اس میں Readability بھی ہے، کیوں کہ کسی اور شخص نے کیا ہے۔ ’بہاؤ‘ کا بھی ہوچکا ہے، پروفیسر سفیر اعوان نے کیا ہے، ’راکھ‘ کا بھی ہوچکا ہے، یہ ابھی شایع ہوں گے۔ البتہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اگر انگریزی میں ترجمہ ہو، تو وہ بین الاقوامی قاری تک بھی پہنچے۔ ورنہ یہ لاحاصل مشق ہے۔ گھر کی بات گھر ہی میں رہ جاتی ہے۔ اس میں حکومت کو بھی کردار ادا کرنا چاہیے۔‘‘ ہم نے ذہن میں کلبلاتا ایک سوال داغا؛ کیا اردو زبان میں بڑا ناول لکھنے کی سکت نہیں؟ کہنے لگے، ’’اردو ایک نومولود زبان ہے، اس کی اپنی محدودات ہیں۔ آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ اِس کی عمر کیا ہے۔ فارسی، عربی اور انگریزی کی عمر طویل ہے۔ ’مراۃالعروس‘ اور ’امراؤ جان ادا‘، جو اردو کے ابتدائی ناولز ہیں، وہ ناول کی تعریف پر پورے اترتے ہی نہیں، اس زمانے میں دنیا میں کیا کچھ لکھا جارہا تھا۔ تو اردو کی اتنی عمر نہیں ہے۔‘‘ لاہور کا عشق ان کی رگوں میں خون بن کر دوڑتا ہے۔ اس تعلق پر کہتے ہیں،’’کیوں کہ میں پلا بڑھا لاہور میں ہوں، گو میرے خاندان کا پس منظر دیہات کا ہے۔ کچھ روز قبل میں لاہور کے سب سے قدیم گورا قبرستان میں گیا۔ اس میں امریکا سے آئے ریوینٹ فورمین کی قبر تھی، جسے دیکھ کر میں سناٹے میں آگیا، کیوں کہ نام کے نیچے لکھا تھا:’فاؤنڈر آف رنگ محل مشن ہائی اسکول اینڈ فارمن کرسچن کالج لاہور‘۔ اب میں رنگ محل اسکول کا پڑھا ہوا ہوں، میرے بچے فارمن کرسچن کالج کے پڑھے ہوئے ہیں۔ اب یہ ربط کسی اور شہر کے ساتھ نہیں بن سکتا۔ مختصراً یہ کہ میرے پاس دنیا کے بڑے بڑے شہروں میں مستقل قیام کے بہت اچھے مواقع تھے، مگر میں نے لاہور کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا۔‘‘ ہم نے کہا، کبھی بڑے بڑے ادیب کالم لکھا کرتے تھے، مگر اب یوں لگتا ہے کہ سیاسی کالم جلد ادبی کالموں پر غالب آجائیں گے۔ تارڑ صاحب کہنے لگے،’’سیاسی کالم اب ادبی کالموں پر غالب آگئے ہیں۔ سیاسی کالموں کی یوں اہمیت ہے کہ ان کے ذریعے آپ کسی کے لیے خطرہ ثابت ہوسکتے ہیں، کسی کے دوست ثابت ہوسکتے ہیں۔ کوئی آپ کو نواز سکتا ہے، گاڑی دے سکتا ہے۔ ادبی کالم لکھنے کا اس تناظر میں تو کوئی فائدہ نہیں۔ مگر میری مجبوری تھی کہ میں ادبی کالم ہی لکھ سکتا تھا۔ (ہنستے ہوئے) ورنہ مجھے بھی کوئی بنگلا یا گاڑی دے دیتا۔ خیر، یہ صنف اب زوال ہی کی جانب جارہی ہے۔‘‘ روانگی کے سمے ہم نے سوال کیا، آپ نے ہمیشہ خود کو چیلینج کیا ہے، اب اگلا چیلینج کیا ہے؟ کہنے لگے،’’کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ ہوسکتا ہے، کچھ نہ لکھوں، اب سکت کم ہوتی جارہی ہے۔ لکھنے کے لیے طاقت، سکت چاہیے۔ کالم میرا ذریعہ معاش ہے، وہ لکھتا رہوں گا، اُسے ادب شمار نہیں کرتا۔ میرے خیال میں کافی لکھ لیا ہے۔ کوئی نئی چیز نہ آجائے، تو شاید کچھ نہ لکھوں۔‘‘ ٭ روحی بانو کا خلا کیوں پُر نہیں ہوگا؟ روحی بانو اور تارڑ صاحب ٹی وی ڈراموں میں ساتھ جلوہ گر ہوئے، دوران گفتگو اس بے بدل اداکارہ اور اس کے المیوں پر بھی بات ہوئی۔ کہنے لگے، ’’کئی المیے ایسے ہوتے ہیں، جو معاشرہ آپ پر نافذ کردیتا ہے۔ وہ دوسروں کی طرف سے ہوتے ہیں۔ روحی کے مسائل پر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ایک طرف گورنمنٹ کالج کے فلسفی طالب علم تھے، دوسری طرف ان کا گھر تھا۔ وہ اکثر اپنے پاگل پن میں مجھ سے کہا کرتی کہ ’تم میرے ہیرو ہے، مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔‘ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ فلاں کا خلا پُر نہیں ہوگا، میں اس پر کوئی خاص یقین نہیں رکھتا۔ البتہ جتنے بھی لوگ گئے، ان میں میرے نزدیک روحی وہ واحد شخصیت ہے، جس کا خلا پر نہیں ہوگا ۔ اس جیسی اور بھی اچھی، خوب صورت، باصلاحیت اداکارئیں آئیں گی، لیکن اس کے حسن میں جو حزن ہے، اور اس کی اداکاری میں جو سوگواری ہے، اور پھر اُس کی جو بے ساختگی اور پاگل پن ہے، وہ ہمیں پھر نہیں ملے گا، یہ کاک ٹیل وہی بنا سکتی ہے۔‘‘ ٭میں، انتظار حسین اور پرندے انتظار حسین اور مستنصر حسین تارڑ، شاید یہ دو ہی ادیب ہیں، جنھوں نے زندگی کے بڑے حصے فقط لکھا، کوئی ملازمت نہیں کی۔ انتظار صاحب کا فکشن بھی موضوع بحث بنا۔ کہتے ہیں،’’انتظار صاحب اور ہمارے محور مختلف تھے۔ ہماری ثقافت، زبان، زندگی کے بارے میں رویے مختلف تھے۔ وہ ادب برائے ادب کے قائل تھے، ہم تھوڑے بہت ادب برائے زندگی کے قائل تھے۔ اُن کا ماخذ اساطیر تھی۔ البتہ انھوں نے جو کچھ لکھا، اس کے گہرے اثرات ہیں۔ ان کے بغیر اردو ادب کی تاریخ مکمل نہیں ہوسکتی۔ ان کا اپنا دبستان ہے، اپنا اسکول ہے۔ میر ا اور اُن کا جو تھوڑا بہت واسطہ تھا، وہ پرندوں کے حوالے سے تھا۔ وہ بھی پرندوں میں دل چسپی رکھتے تھے، اور باقاعدہ مجھ سے پوچھا کرتے تھے۔ تو قدرت کے ساتھ، پرندوں اور مناظر کے ساتھ جو لگاؤ تھا، وہ ہم دونوں میں یکساں تھا۔‘‘ ٭لاہور لحاظ نہیں کرتا تارڑ صاحب نے ایک بار کہا تھا کہ انتظار حسین کو انتظار حسین بنانے میں لاہور نے کلیدی کردار ادا کیا، تو ہم نے پوچھا، کیا لاہور کی برکات سے آپ بھی مستفید ہوئے؟ کہا،’’بالکل، میں اُس کے بیچ میں موجود تھا۔ ہماری بیجوں کی ایک دکان تھی۔ ادھر جسٹس کیانی، ملکہ پکھراج آتی تھیں۔ مرزا ادیب ادھر آیا کرتے تھے، اشفاق احمد کا گزر ہوتا تھا۔ ٹی ہاؤس میں لیجنڈز بیٹھا کرتے تھے۔ کشورناہید، جمیلہ ہاشمی، ساحرہ کے گھر میں، میرے گھر میں، آپا حجاب کے گھر میں محفلیں ہوتی تھیں۔ اُن کا اثر ہوا ہے۔‘‘ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ لاہور آدمی کی مالی حیثیت سے متاثر نہیں ہوتا۔ ایک واقعہ بھی سنایا۔ ’’ایک بار زبیر رضوی، جو بہت اچھے شاعر اور ’ذہن جدید‘ کے مدیر تھے، لاہور آئے، تو ہم نے حلقہ ارباب ذوق میں بلایا۔ حبیب جالب کی صدارت تھی، زبیر رضوی نے اپنی ایک نظم سنائی، جس پر کوئی ردعمل نہیں آیا۔ بلکہ ایک مصرعے پر روحی بانو بے تحاشہ ہنسنے لگیں۔ بڑی مشکل سے اُنھیں چپ کروایا۔ تب حبیب جالب نے کہا:’میاں صاحب زادے، کوئی کام کی چیز ہے، تو سناؤ، یہ لاہور ہے۔‘ تب انھوں نے ایک غزل سنائی، جس پر انھیں داد ملی، بعد میں انھوں نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ جب میں دہلی میں یہ نظم سناتا ہوں، تو پچاس ہزار کا مجمع کھڑا ہوجاتا ہے۔ میں نے کہا، یہی فرق ہے لاہور اور دہلی میں، لاہور لحاظ نہیں کرتا۔‘‘ ٭ کراچی شہر نہیں ہے، جزیرہ ہے! کراچی بھی آنا جانا رہتا ہے۔ پوچھا، اِس شہر کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کہنے لگے،’’کراچی شہر نہیں ہے، یہ ایک تجارتی حب ہے۔ لاہور اور کراچی کے مزاج میں بہت فرق ہے۔ اِس کا اپنا مزاج ہے۔ میں نے لٹریچر فیسٹول میں کہا تھا کہ کراچی ایک جزیرہ ہے، یہ شاید دیگر شہروں سے کٹا ہوا ہے۔‘‘ ٭مدینہ منورہ اور ایک غیرمطبوعہ ناول ہم نے پوچھا، آپ نے دنیا کے کئی شہر دیکھے، کون سا شہر بار بار دیکھنے کو جی چاہتا ہے؟ کچھ ساعت توقف کیا، پھر کہنے لگے،’’مدینہ منورہ۔ میرا اس شہر سے ایک روحانی تعلق ہے۔ میں نے ایک ناول لکھ رکھا ہے، کسویٰ کا سوار۔ ساڑھے تین سو صفحات کا ہے، رسول کریمﷺ کی زندگی پر، مگر اُسے میں ابھی شایع نہیں کروارہا۔ خیر، تو ایک ذاتی قسم کا تعلق ہے۔ البتہ میں روایتی معنوں میں مذہبی نہیں۔ اس شہر میں بار بار جانے کی خواہش رسول اللہ ﷺ کی وجہ سے ہے۔ میری یہ بھی آرزو ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک فلیٹ لے کر دو تین ماہ نارمل زندگی بسر کروں، لوگوں سے ملوں، چلوں پھروں۔‘‘ The post کبھی شہرت کو سنجیدہ نہیں لیا، ’’بہاؤ‘‘ جیسا ناول اب خود بھی نہیں لکھ سکتا appeared first on ایکسپریس اردو.
0 notes